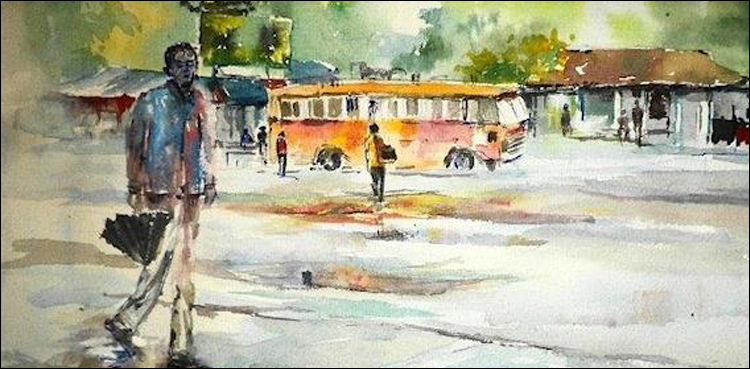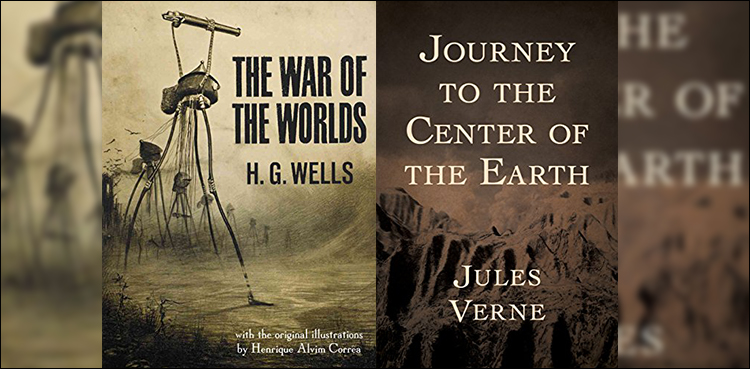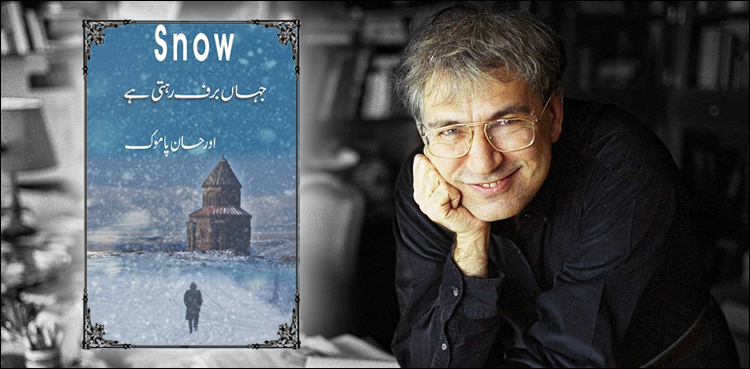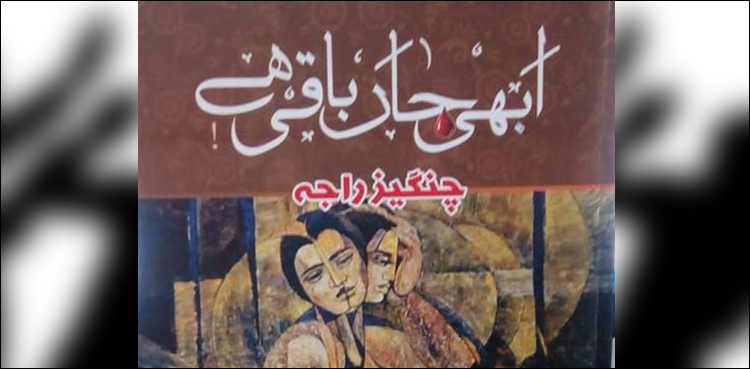نوٹ: یہ طویل ناول انگریزی سے ماخوذ ہے، تاہم اس میں کردار، مکالموں اور واقعات میں قابل ذکر تبدیلی کی گئی ہے، یہ نہایت سنسنی خیز ، پُر تجسس، اور معلومات سے بھرپور ناول ہے، جو 12 کتابی حصوں پر مشتمل ہے، جسے پہلی بار اے آر وائی نیوز کے قارئین کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔
گزشتہ تمام اقساط پڑھنے کے لیے یہ لنک کھولیں
ڈریٹن سہ پہر کو ہوٹل کے کمرے میں جاگا۔ اس نے ہوٹل کی کھڑکی کے باہر کے شٹر کو ہوا میں ہلتے ہوئے سنا۔ اس نے دل میں کہا باہر کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہوگی۔ وہ نیچے لابی کی طرف آیا۔ خزاں کی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی تو اس نے کوٹ کے کالر سے گردن چھپا لی۔ پہلان کو اس نے رپورٹ دینی تھی، لیکن اس وقت اسے بھوک لگ رہی تھی، وہ ہوٹل سے باہر نکلا اور اسی ریسٹورنٹ کی طرف چلا گیا جہاں اس نے پہلے بھی کھانا کھایا تھا۔
وہ ریسٹورنٹ میں داخل ہوا تو گوشت کی تازہ پائی اور کارنش پیسٹری کی مہک نے اس کی بھوک ایک دم سے بڑھا دی۔ ویٹریس ایگنس نے اسے پہچان لیا، اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار پھیل گئے۔ وہ مینیو لے کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی تو ڈریٹن نے بدتمیزی سے مینیو لے کر اسے کہا کہ وہ ’دفع‘ ہو جائے۔ ڈریٹن نے پنیر اور پیاز کی بریڈیز، ڈیڑھ درجن ساسیج رولز اور پھلیاں اور چپس کی پلیٹ منتخب کی، پھر اس نے ایگنس کو اشارے سے بلانا چاہا لیکن اس نے نظر انداز کر دیا، اس پر ڈریٹن آگ بگولا ہو گیا، اور کرسی پر کھڑے ہو کر چلایا اور مغلظات بکنے لگا۔ ایگنس اپنے باس کے اشارے پر خاموشی سے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ڈریٹن نے کہا کہ اسے یہ، یہ اور یہ چاہیے، وہ بھی آن کی آن میں۔ جب ایگنس مڑ کر جانے لگی تو ڈرٹین نے ڈپٹ کر پوچھا: ’’تمھارا مسئلہ کیا ہے؟‘‘
ایگنس نے گھبرا کر کہا: ’’میں آپ کو نہیں بھولی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ آپ ہی تھے جس نے میک ایلسٹر کے گھر کو نقصان پہنچایا تھا۔ ایلسی نے مجھے بتایا۔‘‘
ڈرٹین چونکا: ’’اوہ اس نے ایسا کہا، ٹھیک ہے، مجھے ایلسے کے ساتھ افواہیں پھیلانے کے بارے میں بات کرنی پڑے گی، تم جلدی میرا کھانا لاؤ اب۔‘‘
ریسٹورنٹ میں موجود بہت سے لوگ خطرے کا احساس کرتے ہوئے اٹھ کر باہر نکل گئے۔ ایسے میں دروازہ کھلا اور ایلسے اندر داخل ہو گئی۔ ایگنس گھبرا کر ایلسے کے پاس بھاگی اور آہستگی سے کہا: ’’بہتر ہے تم ابھی چلی جاؤ۔ وہ آدمی یہاں ہے اور…‘‘
لیکن ڈریٹن نے بھی اسے دیکھ لیا تھا، وہ اٹھ کر اس کے پاس گیا اور بازو سے پکڑ کر کہا: ’’ذرا میرے ساتھ بیٹھ جاؤ یہاں، ہم تھوڑی بات کریں گے۔‘‘ اس نے ایلسے کو تقریباً گھسیٹا اور میز پر لے جا کر کرسی پر بٹھا دیا۔ ایسے میں ایگنس نے اپنے باس ایوان کے کان میں کچھ سرگوشی کی اور وہ ایپرن کھول کر دبے پاؤں دروازے سے ریسٹورنٹ سے باہر نکل گیا، خود ایگنس کاؤنٹر کے پیچھے گئی اور ایک بھاری سیاہ کڑاہی اٹھالی، کہ اگر ڈریٹن نے ایلسے کو تکلیف دینے کی کوشش کی تو وہ اس سے حملہ آور ہوگی۔
ڈریٹن کی زہر خند آواز گونجی: ’’ایلسے، تمھیں دیکھ کر اچھا لگا لیکن میں نے سنا ہے کہ تم میرے بارے میں شہر بھر میں انٹ شنٹ افواہیں پھیلا رہی ہو۔ کیا یہ سچ ہے؟‘‘
’’مم … میں نہیں سمجھی، تمہارا کیا مطلب ہے؟‘‘ ایلسے پوری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ ڈریٹن نے کہا کہ وہی بات کہ میں نے مک ایلسٹر کے گھر کو برباد کیا۔ ایلسے نے کہا یہ موضوع اٹھا تھا اور ایک بار آپ کا نام بھی آیا بس۔ ڈریٹن بولا ’’اوہ، اور میرا نام کس نے اٹھایا؟ کیا تم نے میرا نام اٹھایا تھا ایگنس، اور میرا کھانا کہاں ہے؟‘‘ اس نے ایگنس کی طرف مڑ کر کہا۔ ایگنس نے کڑاہی نیچے رکھ دی اور اس کا کھانا ٹرے میں سجا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔
ڈریٹن نے ایک ساسیج نیپکن پر رکھ کر ایلسے کی طرف بڑھایا اور کہا تم بھی کھاؤ۔ ایلسے اس کا انداز دیکھ کر انکار نہیں کر سکی، ڈریٹن نے کہا ٹماٹر کی چٹنی بھی لو نا۔ یہ کہہ کر اس نے بوتل اٹھائی لیکن اس میں سے چٹنی زور ڈال کر نکل سکتی تھی۔ اس لیے ڈریٹن نے اس کی باریک نلی ایلسے کے سینے کی طرف کر کے اچانک اسے دبایا اور چٹنی ایک دھار کی طرف نکلی اور ایلسے کا سفید بلاؤز رنگین ہو گیا۔ ڈریٹن نے اداکاری کی، اوہ میں نے گڑبڑ کر دی۔ پھر اس نے چپس اٹھا کر ایلسے کے کپڑوں پر پڑی ٹمیٹو ساس میں ڈبوئی اور منھ میں ڈال دی۔ ’’کافی لذیذ ہے۔‘‘ اس نے کہا اور ساسیج رول کھانے لگا۔ ایلسے اٹھ کر جانے لگی تو اس نے اسے دوبارہ بٹھا دیا اور وہ تب تک بیٹھی رہی جب تک ڈریٹن نے اپنا کھانا ختم نہ کر لیا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے سرد لہجے میں کہا ’’اگر میں نے شہر میں مزید ایک بھی افواہ سنی تو میں تمھارے ’بی اینڈ بی‘ آ کر تم سے ملوں گا، سمجھ گئی نا؟‘‘
ایلسے نے ڈر کے مارے ہاں میں سر ہلایا، اس کے گالوں پر آنسو بہنے لگے تھے۔ ڈریٹن نے اچانک میز پر پڑی پلیٹ اٹھا کر فرش پر پٹخ دی۔ پلیٹ میں بچا کھانا فرش پر بکھر گیا۔ پھر وہ ہنستے ہوئے اٹھا اور بل ادا کیے بغیر باہر نکل گیا۔ وہ جیسے ہی گلی مڑنے والا تھا عین اسی وقت ایوان بھی ایک پولیس افسر کے ساتھ واپس آیا۔ ڈریٹن اس سے بے خبر تھا اور سوچ رہا تھا کہ بہتر ہے کہ وہ اب قلعے جا کر پہلان جادوگر کو کل رات کے بارے میں رپورٹ دے۔
جاری ہے ۔۔۔