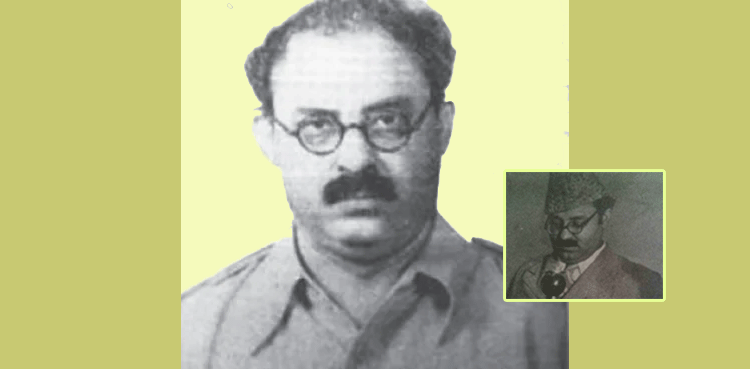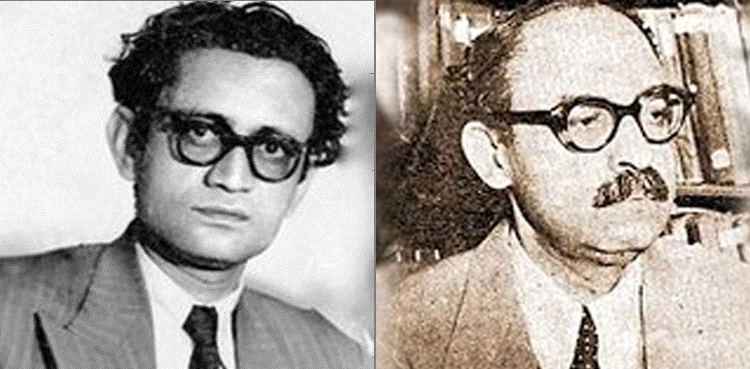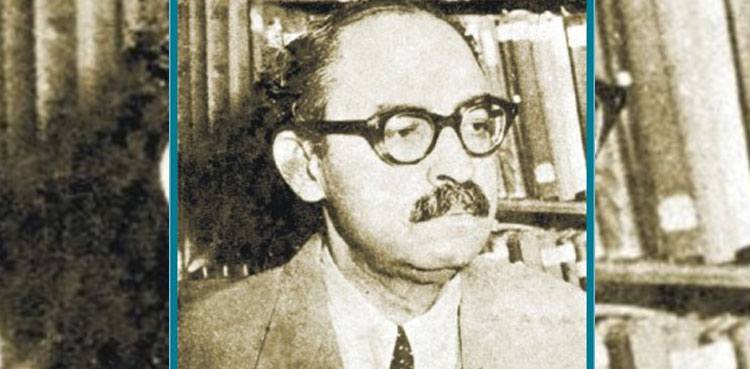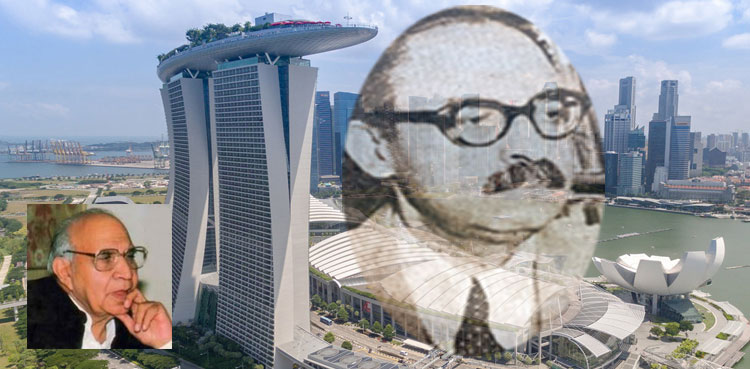ہندوستان کی سرزمین پر کبھی ان بادشاہوں، راجاؤں اور نوابوں کی حکومت تھی جو علم و فنون کے رسیا بھی تھے اور شعر و ادب کا اعلیٰ ذوق بھی رکھتے تھے۔ ان کے دربار میں موسیقار، گویّے، اہلِ قلم شخصیات کے ساتھ بھانڈ اور مسخرے بھی حاضر رہتے تھے۔ ان بھانڈ اور مسخروں کی روزی روٹی ان درباروں سے جڑی ہوئی تھی، لیکن محلّات کے اجڑنے کے ساتھ کئی پیشے اور فن کار بھی مٹ گئے ہیں۔
مشاہیرِ ادب کے بارے میں تحریریں اور ادبی مضامین پڑھنے کے لیے لنک کھولیں
یہ چراغ حسن حسرت کا ایک مضمون ہے جس میں انہی کرداروں کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اردو کے بلند پایہ ادیب، انشا پرداز، جیّد صحافی اور شاعر چراغ حسن حسرت کی تحریر پڑھیے:
بھاٹ اور سوانگی کا نام سنتے ہی ایک پرانا مرقع میری نظر کے سامنے آگیا، جس کے نقوش مدھم پڑگئے ہیں۔ رنگ پھیکے پھیکے، لکیریں دھندلائی ہوئی۔ اس مرقع کی کچھ تصویریں اجنبی معلوم ہوتی ہیں، کچھ جانی پہچانی۔
کیونکہ ہر چند میرے اور اس کاروانِ رفتہ کے درمیان سیکڑوں برس کی مدت حائل ہے۔ زمانے نے غبار کا ایک پردہ سا تان رکھا ہے۔ جس نے میری نظروں کو دھندلا دیا ہے، تاہم میں نے ہندوستان کے ماضی کے متعلق جو کچھ پڑھا ہے، بزرگوں کی زبانی جو کچھ سنا ہے اس نے بیگانگی اور نا آشنائی کی شدت کو کس قدر کم کر دیا ہے۔
میں ان تصویروں کے پھیکے پھیکے نقوش، مبہم خد و خال پر غور کرتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یکایک ان کے دھندلے خطوط ابھر آئے۔ رنگ شوخ ہوگئے۔ ان کے لب ہلنے لگے۔ یعنی ان تصویروں میں جان سی پڑ گئی۔ اب جو سوچتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مٹی مٹی سنہری لکیریں راج محل کے ستون ہیں جو ایک عظیم الشان عمارت کو سہارا دیے کھڑے ہیں۔ یہ آڑے ترچھے خط، یہ مدھم مدھم نقش و نگار، راج سنگھاسن، جڑاؤ مکٹ، سنہری مسندیں، پٹکوں کے حاشیے اور تلواروں کے قبضے ہیں۔ راج محل میں دربار لگا ہے۔ راجہ سر پر مکٹ رکھے سنہری تاج پہنے چھپر تلے بیٹھا ہے۔ بڑی بڑی مونچھیں، کھلتا ہوا گیہواں رنگ، کھلی پیشانی، سڈول جسم، تلوار کے قبضے پر ہاتھ، دونوں طرف درباریوں کی قطار، یکبارگی ایک شخص آگے بڑھتا ہے اور پراکرت کی ایک نظم پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔
الفاظ کی شوکت، مصرعوں کے در و بست سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی رزمیہ نظم ہے۔ لفظ لفظ میں تلواروں کی بجلیاں کوندتی اور سنانیں چمکتی نظر آتی ہیں۔ لیکن یہ رزمیہ نظم نہیں قصیدہ ہے، جس میں موقع کی مناسبت سے راجہ کی تعریف کے ساتھ ساتھ اس کے اور اس کے باپ دادا کے کارنامے بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن نظم میں بلا کی روانی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک غضب ناک دریا پہاڑوں کو چیرتا، درختوں کو جڑ سے اکھیڑتا، چٹانوں کو توڑتا پھوڑتا اپنی رو میں بہاتا لیے جارہا ہے۔ جگہ جگہ دیو مالا کی پر لطف تلمیحیں ہیں، جنہوں نے کلام میں زیادہ زور پیدا کر دیا ہے۔ کہیں شوخی کے جلال و غضب کا ذکر جس کی آگ نے کام دیو کو جلا کر راکھ کر ڈالا تھا، کہیں سورگ کے راجہ اندر کے جنگی ہتھیاروں یعنی اس کے بجر اور دھنش اور اس کی سواری کے ہاتھی ایراوت کی طرف اشارے ہیں، جو سیہ مست بادلوں کی طرح جھوم جھوم کے چلتا ہے۔
یہ عشق و وفا کی شاعری نہیں جس میں ساون کی راتوں، آم کے بور، کوئل کی کوک، پپیہے کی پکار، کنول، بھونرا اور مالتی کی جھاڑیوں کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ درباری شاعری ہے جن میں رزمیہ شاعری نے مدحیہ شاعری کے ساتھ مل کے عجب شان پیدا کر دی ہے اور یہ شخص راجہ کے دربار کا بھاٹ ہے جو ایک خاص تقریب پر اپنی زبان آوری کا کمال دکھانے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔
بھاٹ اور کوی میں بڑا فرق یہ تھا کہ کوی کے لیے کسی دربار سے تعلق رکھنا اور مدحیہ قصیدے کہنا ضروری نہیں ہوتا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ بعض گویوں کو بھی درباروں سے تعلق رہا ہے لیکن دربار میں بھی وہ بھاٹوں سے اونچی حیثیت رکھتے تھے۔ بعض کوی ایسے تھے جن کی زبان راجاؤں کی مدح سے آلود نہیں ہوئی۔ بعض گویوں نے بادشاہوں کی تعریف بھی کی ہے لیکن ان کا انداز الگ تھا۔ بھاٹوں کو دراصل ان کی شاعری کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کی زبان آوری کی وجہ سے قابلِ قدر سمجھا جاتا تھا اور بعض بھاٹ تو خود شعر کہنا نہیں جانتے تھے بلکہ پرانے شاعروں کا رزمیہ کلام پڑھ کے سنا دیتے تھے۔ یا شاعروں کے کلام میں تھوڑی سی قطع و برید کر کے اسے موقع کے مناسب بنا لیتے تھے۔
پرانی کتابوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کوی عام طور پر ترنم سے شعر پڑھتے تھے اور بھاٹ تحت اللفظ میں اپنا کمال دکھاتے تھے۔ اس کے علاوہ انہیں راجاؤں کے نسب نامے اور ان کے بزرگوں کے کارنامے بھی یاد ہوتے تھے، جنہیں وہ بڑے مبالغے کے ساتھ بیان کرتے تھے۔ عربوں میں بھی نسب نامے یاد رکھنا بڑا کمال سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ جو لوگ نسب نامے یاد رکھتے تھے وہ نساب کہلاتے تھے اور بڑی عزت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ لیکن ہندوستان کے بھاٹوں کو عرب کے نسابوں سے کوئی نسبت نہیں۔
غرض بھاٹ اور کوی کے فرق کو چند لفظوں میں بیان کرنا ہو تو یہ کہنا چاہیے کہ کوی اپنے تأثرات بیان کرتا ہے اور بھاٹ کو ذاتی تأثرات سے کوئی واسطہ نہیں۔ وہ ایک مقررہ فرض بجا لاتا ہے اور بس۔
بھاٹوں نے اور کچھ کیا کیا نہ کیا، کم از کم راجاؤں اور بڑے امیروں کے دل میں جوشِ سماعت ضرور زندہ رکھا۔ وہ ان لوگوں کے بڑوں کے قابلِ فخر کارنامے اس انداز میں بیان کرتے تھے کہ سننے والوں کی رگوں میں خون موج مارنے لگتا تھا۔ کڑکیت بھی انہیں بھاٹوں کے بھائی بند تھے جو جنگ کے موقع پر سپاہیوں کو لڑائی کے لیے ابھارتے تھے۔ پرانے زمانے کی لڑائیوں میں یہ دستور تھا کہ جب دو فوجیں آمنے سامنے ہوتی تھیں تو پہلے دونوں کے کڑکیت اپنی اپنی فوجوں کے سامنے کھڑے ہو کر کڑکا کہتے تھے۔ یہ کچھ اشعار ہوتے تھے جن میں دنیا کی بے ثباتی کے ذکر کے ساتھ ساتھ اپنی طرف کے سپاہیوں کی بہادری کی تعریف کی جاتی تھی۔ یہ رسم عرب میں بھی تھی۔ اسلام سے پہلے شاعر بھی یہ خدمت انجام دیتے تھے۔ پھر لڑائیوں میں عورتیں بھی دف بجا بجا کے گیت گاتیں اور اپنی طرف سے شہ سواروں کو لڑائی پر ابھارتی تھیں۔ عربوں کے اسلام لانے کے بعد یہ رسم مٹ گئی۔
اشعار کے ذریعے فوج کو برانگیختہ کرنے کا کام صرف شاعروں کے ذمہ رہ گیا۔ لیکن اس غرض کے لیے خاص طور پر شاعر نہیں رکھے جاتے تھے کیونکہ جس زمانے کا یہ ذکر ہے اس زمانے میں عربوں میں شاعروں کی کثرت تھی۔ ہر فوج میں سیکڑوں شاعر ہوتے تھے اور اکثر اوقات تو خود سردار لشکر کو شاعری میں خاصا درک ہوتا تھا۔
ہندوستان کی بعض ریاستوں میں اب بھی بھاٹ موجود ہیں۔ جو دسہرہ اور بسنت کے درباروں میں شادی بیاہ کے موقع پر گیت سناتے ہیں۔ کوئی بیس سال ہوئے مجھے ایک بھاٹ سے ملنے کا اتفاق ہوا تھا۔ بڑا ذہین شخص تھا اگرچہ پڑھنا لکھنا واجبی سا ہی جانتا تھا لیکن برج بھاشا پر بڑا عبور رکھتا تھا اور حسبِ موقع فوراً شعر جوڑ لیتا تھا۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ اس کا اپنا کلام تھا۔ وہ پرانے شاعروں کے کلام میں موقع کی مناسبت سے ترمیم کر کے شعر گڑھ لیتا تھا۔
اس مرقع میں ایک اور تصویر بھی ہے۔ شیشم کے پیڑ تلے گاؤں کے لوگ اکٹھے ہیں۔ بیچ میں کچھ آدمی ناٹک کر رہے ہیں لیکن نہ پردے ہیں نہ خاص لباس۔ ایک آدمی سارنگی بجا رہا ہے، دوسرا ڈھولک پر تال دے رہا ہے اور تیسرا اونچی لے میں کچھ گا رہا ہے۔ یہ ایک لمبی نظم ہے جس کے مطلب کو یہ شخص ایکٹنگ کے ذریعے واضح کر رہا ہے۔ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی جواب دیتا ہے، لیکن موقع کے لحاظ سے لب و لہجہ بدل جاتا ہے۔ یہ سوانگیوں کی منڈلی ہے اور نل دمینتی کی کہانی ان کا موضوع ہے۔
سو انگیوں کی منڈلی میں زیادہ آدمی بھی ہوتے تھے۔ جو مختلف پارٹ ادا کرتے تھے۔ اپنی اپنی بساط کے مطابق بھیس بدلنے کا سامان بھی رکھتے تھے۔ لیکن اکثر منڈلیاں سامان کے بغیر بھی کام چلا لیتی تھیں۔ دیہات میں اب بھی ان لوگوں کی منڈلیاں نظر آجاتی ہیں، لیکن ان کی اگلی سی قدر نہیں رہی۔
سوانگوں اور رہس دھاریوں میں بہت تھوڑا فرق ہے۔ رہس دھاریوں کا موضوع دھارمک ڈرامے ہیں۔ خصوصاً سری کرشن جی کی زندگی۔ ان کا اصل وطن برج اور متھرا کا علاقہ ہے جہاں کرشن جی کی زندگی کا ابتدائی زمانہ گزرا۔ سوانگی ہر طرح کے کھیل دکھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سوانگیوں کی سرگرمیاں صرف دیہات تک محدود رہ گئیں۔ رہس دھاری شہروں تک پہنچے اور جہاں تک گئے ہاتھوں ہاتھ لیے گئے۔ اودھ کے آخری بادشاہ واجد علی شاہ مرحوم کو رہس کا بڑا شوق تھا۔ چنانچہ شاہی محلوں میں رہس ہوتی تھی، بادشاہ کنھیا بن کے چھپ جاتے تھے اور گوپیاں انہیں ڈھونڈنے نکلتی تھیں۔ ہندوستان میں تھیٹر کی بنیاد بھی رہس ہی سے پڑی۔ یعنی رہس کو سامنے رکھ کر اندر سبھا کا ناٹک کھیلا گیا جو ہندوستان میں تھیٹر کا سنگ بنیاد سمجھا جاتا ہے۔
سوانگیوں اور رہس دھاریوں کے آغاز کے متعلق تحقیق کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہندوستانی ڈرامہ جو بڑے عروج پر پہنچ چکا تھا، جب راجوں مہاراجوں کی سرپرستی سے محروم ہوگیا تو اس کی جگہ سوانگ اور رہس نے لے لی۔ لیکن یہ بات وثوق سے نہیں کہی جا سکتی، ممکن ہے کہ سوانگ ہندوستانی ڈرامے کی ابتدائی صورت ہو۔ جب ڈرامے نے ترقی کی تو کالی داس، بھوبھوتی، شدرک بھاش، ہرش وغیرہ جیسے مصنف مل گئے تو وہ حکومتوں کے مرکزوں اور بڑے بڑے شہروں میں تو بہت اونچے درجے پر جا پہنچا۔ لیکن دیہات میں اس کی حالت جوں کی توں رہی۔ یعنی اس نے سوانگ کے دائرے سے قدم باہر نہیں نکالا۔
باقی رہے رہس دھاری، تو ان کا معاملہ ہی الگ ہے کیونکہ رہس کا موضوع کرشن جی کی زندگی ہے، اور یہ اور بات ہے کہ بعض رہس دھاریوں نے اپنے موضوع کو محدود نہیں رکھا اور آگے چل کر مختلف قسم کے ناٹک دکھانے شروع کر دیے۔ رہس دھاری بھی اگرچہ سوانگیوں ہی کا ایک گروہ ہیں لیکن انہیں جو عروج حاصل ہوا وہ سوانگیوں کو کبھی نصیب نہیں ہو سکا۔ اکثر رہس دھاری بھیس بدلنے میں خاص اہتمام کرتے ہیں، پھر انہیں راگ ودیا میں بھی کسی قدر مہارت ہوتی ہے۔ اس کے برعکس سوانگی صرف دیہاتیوں کے ڈھب کی سیدھی سادی دھنیں یاد کرلینا کافی سمجھتے ہیں۔ رہس دھاریوں کے قدر دان اب صرف چھوٹے چھوٹے شہروں اور قصبوں میں رہ گئے ہیں۔ بڑے بڑے شہروں میں انہیں کوئی نہیں پوچھتا۔
بہروپیے بھی سوانگیوں کے بھائی بند ہیں۔ سوانگیوں کی منڈلیاں ہوتی ہیں۔ بہروپیا اپنے ہنر کی بدولت کماتا کھاتا ہے۔ بہروپیے طرح طرح کے بہروپ بھرتے ہیں اور جو لوگ ان کے بہروپ سے دھوکا کھا جاتے ہیں ان سے انعام کے طالب ہوتے ہیں۔ سوانگ اور بہروپ صرف ہندوستان پر ہی موقوف نہیں۔ ایشیا کے اکثر ملکوں خصوصاً چین میں اب تک ایسی ناٹک منڈلیاں موجود ہیں جو سوانگیوں اور رہس دھاریوں سے بہت ملتی جلتی ہیں اور تو اور یورپ کے دیہات میں جو راہ باٹ سے کٹے ہوئے ہیں ایسی منڈلیاں مل جائیں گی جو پرانے انداز کے چھوٹے چھوٹے ڈرامے دکھاتی ہیں۔
غرض بھاٹ، سوانگی، رہس دھاری، بہروپیے کہنے کو اب بھی موجود ہیں، لیکن اصل میں ان کا زمانہ ختم ہو گیا۔ وہ ہندوستان کی پرانی تہذیب کی آخری یادگار ہیں جو چاہے ملک کے کسی گوشے میں بیس تیس بلکہ سو پچاس تک یوں ہی پڑی رہیں۔ لیکن نئے زمانے میں ان کے لیے کہیں بھی گنجائش نہیں نکل سکتی۔ آج ان کی حیثیت مدھم نقوش کی ہے۔ کل دیکھیے گا کہ یہ پھیکے پھیکے نقوش بھی بالکل مٹ گئے اور سادہ ورق باقی رہ گیا۔