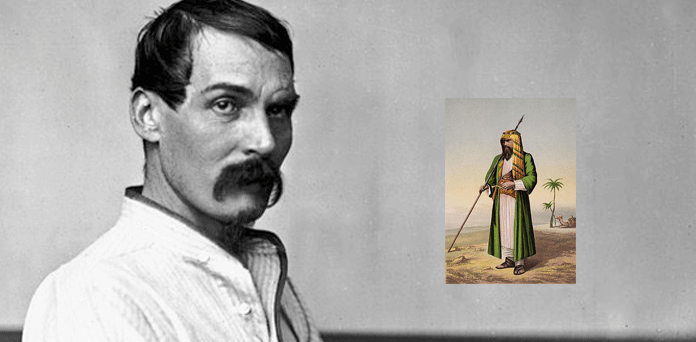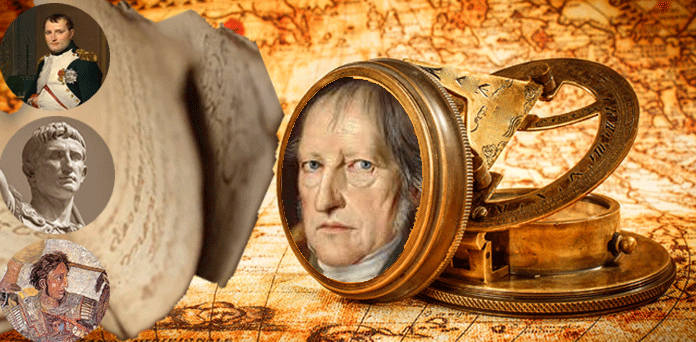ہندوستان میں کمپنی کی حکومت جب مستحکم ہوگئی تو اس کے ساتھ ہی یہ خطرہ بھی لاحق ہوا کہ روس اپنے سیاسی تسلط کو وسطی ایشیا میں بڑھا رہا تھا اور کمپنی کے حلقوں میں یہ تصور عام تھا کہ روس وسط ایشیا پر قبضہ کرتے ہوئے ایران کی مدد سے افغانستان آئے گا اور یہاں سے ہندوستان پر حملہ کرے گا۔ لہٰذا کمپنی کی حکومت نے بخارا، خیواء، یارقند، ہنزہ، ایران اور افغانستان میں مخبروں اور سفارت کاروں کے ذریعے ان علاقوں کے سیاسی حالات، جغرافیائی حدود اور راستوں کی تحقیقات کے لیے معلومات فراہم کیں۔ یہ مخبر سیاحوں اور تاجروں کا بھیس بدل کر ان علاقوں میں گئے۔
ان جاسوسوں میں سے ایک Richard Burton (سنہ ولادت 1821) تھا، جسے عربی اور فارسی کے علاوہ کئی اور دوسری زبانوں پر مکمل عبور تھا۔ بعد میں اس کی شہرت بطور مترجم، مشرقی علوم کا ماہر اور جاسوس کی وجہ سے ہوگئی۔ اس کے کیریئر کا آغاز کمپنی کی فوج میں جس کا کمانڈر چارلس نیپیر تھا، شروع ہوا اور جب چارلس نیپیر نے سندھ پر حملہ کیا تو یہ اس کے ہمراہ تھا۔
رچرڈ برٹن کے کیریئر کا ایک اہم حصہ 1853ء میں حج کا سفر تھا۔ چونکہ مکہ مدینہ میں غیر مسلموں کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس لیے اس نے مسلمانوں کا بھیس بدل کر پہلے خود کو ایرانی اور بعد میں افغان باشندہ کہا۔ چونکہ اسے فارسی زبان پر مہارت تھی اس لیے کسی کو اس کے یورپی ہونے کا شک نہیں گزرا۔ اپنے حج کے سفر کی معلومات کو اس نے نوٹس کے ذریعے محفوظ کر لیا تھا۔ حج کے بارے میں اہلِ یورپ کو یہ تجسس تھا کہ وہاں کیا رسومات ہوتی ہیں اور کیسے حج کیا جاتا ہے۔ رچرڈ بر ٹن سے پہلے بھی کچھ سیاح بھیس بدل کر حج کا سفر کر چکے تھے اور انہوں نے اپنے تجربات اور مشاہدات کو شائع بھی کرایا تھا۔ انہی میں سے ایک (متوفی John Burk Hardt (1817 تھا جس نے ابراہیم کے نام سے مکہ مدینے کا سفر 1814ء میں کیا۔
رچرڈ بر ٹن نے ان یورپی سیاحوں کے سفر ناموں کا مطالعہ کیا تھا، تا کہ وہ خود کو مسلمان ثابت کر کے حج کی مذہبی رسومات کو بھی ادا کر سکے۔ اس وقت حجاز اور نجد کے علاقے ترکوں کے زیر حکومت تھے اور مکہ مدینہ جانے والے راستے حاجیوں کے لیے غیر محفوظ تھے۔ راستے میں عرب بد و قبائل حاجیوں کے قافلوں کو لوٹتے تھے۔ رچرڈ برٹن سفر کی تمام معلومات کو اکٹھا کر کے قاہرہ سے بحری جہاز کے ذریعے جدہ روانہ ہوا۔ اس نے جہاز میں جانے والے مسافروں کا حال بھی لکھا ہے کہ تکالیف اٹھا کر جدہ پہنچتے تھے۔ جدہ سے مدینے تک کا سفر اونٹ اور اونٹنیوں کے ذریعے کیا۔ اس سفر میں اس کا ایک ہندوستانی نوکر بھی اس کے ساتھ تھا۔ برٹن نے بہت جلد عربوں سے دوستانہ تعلقات قائم کر لیے اور ان کی عادات اور رسم و رواج اختیار کر لی۔ خاص طور سے وہ بار بار لکھتا ہے کہ عربوں میں کافی پینے اور تمباکو کے استعمال کرنے کا بہت رواج ہو گیا تھا اور وہ خود بھی ان کے ساتھ اس میں برابر کا شریک تھا۔ برٹن نے پہلے مدینے کا رخ کیا اور قیام کر کے رسول کے مقبرے کی زیارت کی اور پھر حضرت حمزہ کے مزار پر بھی گیا۔ اس دوران وہ پابندی سے نماز پڑھتا تھا اور مسلمانوں کے طور طریقے پر عمل کرتا تھا۔ مدینے کے قیام کے بعد وہ حج کے موقع پر مکہ گیا اور وہاں اس نے حج کی تمام رسومات ادا کیں اور کسی کو یہ شک نہیں ہونے دیا کہ وہ غیر مسلمان ہے۔
حج سے واپسی کے دوران اس نے دو جلد میں اپنے سفر کے حالات لکھے ہیں خاص طور سے اس نے تفصیل کے ساتھ ان رسومات کا ذکر کیا ہے جو حج کے موقع پر کی جاتی ہیں، اسی سفر نامے کے ذریعے اہل یورپ کو مسلمانوں کے حج کے بارے میں مفید معلومات حاصل ہوئیں۔
رچرڈ برٹن کی دوسری اہم تصنیفات میں مشہور عربی داستان الف لیلہ کا انگلش ترجمه The Book of the Thousand Nights and a Night ہے۔ اس نے ہندوستانی جنسیات پر لکھی جانے والی کتاب کاما سوتر اور عربی میں لکھی جانے والی کا Perfumed Garden کے نام سے ترجمہ کیا ہے۔ اس کی خدمات کے عوض رائل سوسائٹی آف جیوگرافی نے اسے اپنا ممبر بنایا اور برطانوی حکومت نے اسے Knighthood یا سر کا خطاب دیا۔ ان تصنیفات کے علاوہ اس نے اور بھی کئی موضوعات پر کتابیں لکھی ہیں۔
1890ء میں اس کی وفات ہوئی اور اس کے مقبرے کو خیمے کی شکل میں تعمیر کیا گیا۔ برٹن کی شخصیت اس لیے اہم ہے کہ اس نے بیک وقت کئی ملکوں کی سیاحت بھی کی، جاسوسی بھی کی۔ غیر ملکی زبانوں پر عبور حاصل کیا اور اپنے تجربات اور علم کو تصنیف و تالیف کے ذریعے دوسروں تک پہنچایا۔ اس سے اس کی ذہانت اور توانائی کا اندازہ ہوتا ہے اور یہ کہ ایک فرد اپنی شہری زندگی میں بیک وقت کئی منصوبوں کو پورا کر سکتا ہے۔
(ڈاکٹر مبارک علی کتاب "ماضی کی داستان” سے اقتباسات)