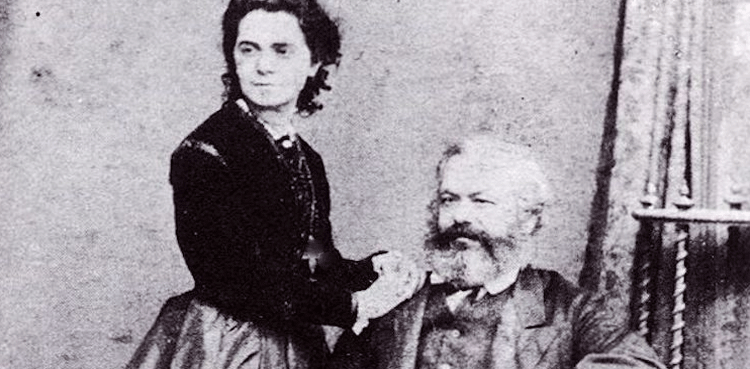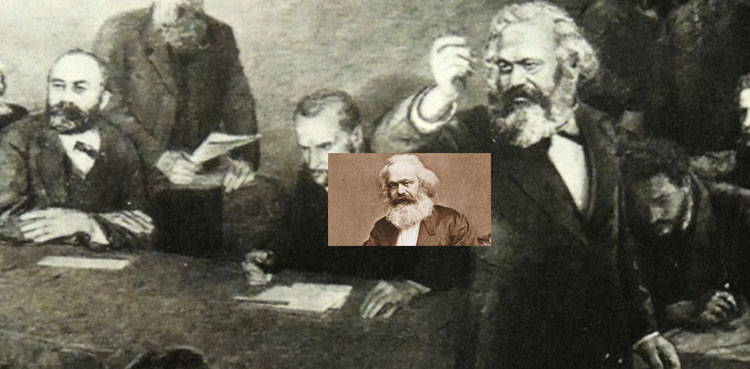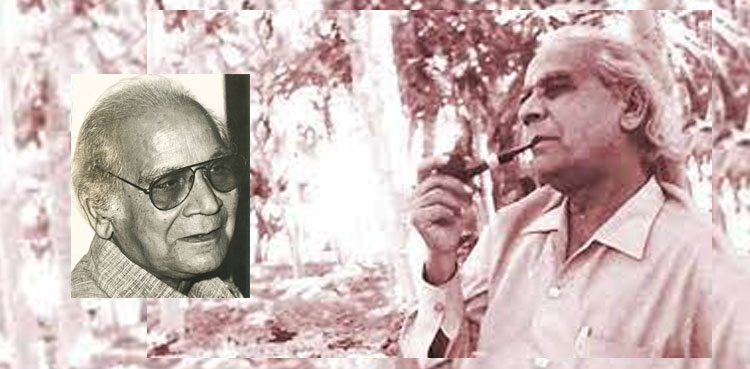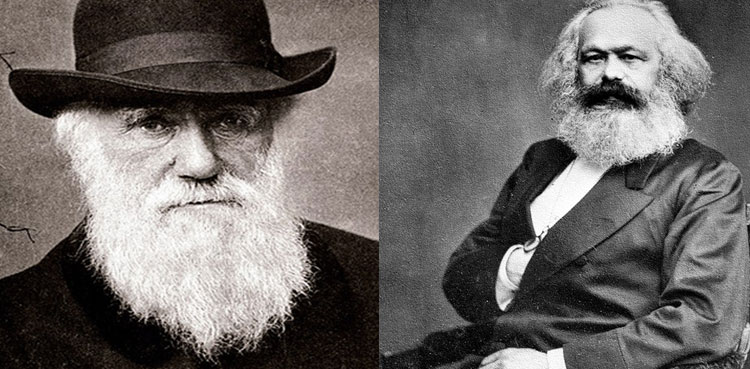انقلابِ روس اور اس کے بعد سوویت یونین کا انجام بلاشبہ تاریخ کے دو عظیم واقعات ہیں جن کا اس خطّے پر ہی نہیں دنیا پر گہرا اثر پڑا اور کئی تبدیلیوں کا سبب بنا۔ 1917ء میں زارِ روس کی حکومت آج ہی کے روز ختم کر دی گئی تھی۔ اسے بالشویک انقلاب یا اکتوبر انقلاب بھی کہا جاتا ہے۔
اس انقلاب کی قیادت لینن کر رہا تھا جس نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے زارِ روس کا تختہ الٹ کر دنیا میں مزدور اور محکوم طبقات کی پہلی حکومت قائم کی۔ لینن انیسویں صدی کے عظیم فلسفی، معیشت دان اور انقلابی کارل مارکس کا معتقد تھا۔ کارل مارکس چاہتا تھا کہ روس میں سرمایہ دارانہ نظام ختم ہو اور اس کے مقابلہ معاشی مساوات قائم ہو اور سماجی ڈھانچے میں انقلابی تبدیلیاں کی جائیں۔ مارکس کا فلسفہ کہتا تھا کہ سرمایہ دارانہ نظام اپنے ہی سماجی ڈھانچے اور متوسط طبقے کا طرزِ زندگی تباہ کر دیتا ہے۔ اِس کے انقلابی فلسفہ سے متاثر ہو کر لینن نے روس میں انقلاب کے لیے آواز بلند کی تھی اور اس کی جدوجہد کام یاب ہوگئی۔
روس میں تبدیلی کی ابتدا 1905ء سے ہوئی اور آہستہ آہستہ انقلاب کی خواہش پورے ملک کے مزدور پیشہ افراد اور پسے ہوئے طبقات کے دل میں ہمکنے لگی۔ وہ سامراجی حکومت کے خلاف صف آراء ہو گئے جس کے نتیجے میں 1917 سے 1919 کے درمیان میں انقلابی جدوجہد مکمل ہوئی۔
روس کے آخری شہنشاہ نکولس دوم تھے جنھیں ان کی بیوی اور پانچ اولادوں سمیت انقلاب کے بعد قتل کر دیا گیا۔ یہ 1918 کا واقعہ ہے۔
انسانی سماج میں طبقات میں منقسم ہونے کے بعد سے یہ محنت کشوں کی سب سے فیصلہ کن فتح تھی۔ بالشویکوں نے بادشاہت کے خلاف سماج کی اکثریت کی حاکمیت کو قائم کیا۔ یہ مارکسی روح کے مطابق ایسا انقلاب تھا جس کے بعد محنت کشوں کو اقتدار مل گیا۔ لینن نے دسمبر 1917ء میں لکھا، ”آج کے اہم ترین فرائض میں یہ شامل ہے کہ محنت کشوں کی آزادانہ پیش قدمی کو پروان چڑھایا جائے۔ اسے ہر ممکن حد تک وسیع کر کے تخلیقی تنظیمی کام میں تبدیل کیا جائے۔ ہمیں ہر قیمت پر اس پرانے، فضول، وحشی اور قابل نفرت عقیدے کو پاش پاش کرنا ہو گا کہ صرف نام نہاد اعلیٰ طبقات، امرا اور امرا کی تعلیم و تربیت پانے والے ہی ریاست کا نظام چلا سکتے ہیں اور سوشلسٹ سماج کو منظم کرسکتے ہیں۔“
انقلاب کے لیے جدوجہد تو بڑے عرصے سے جاری تھی مگر اس کا فوری اثر پہلی جنگِ عظیم میں روس کی شکست کے بعد ہوا تھا۔ اس سے قبل بادشاہت میں عوام اپنی محرومیوں اور مشکلات پر آواز اٹھانے لگے تھے جسے کچلنے کے لیے زارِ روس کے وفادار سپاہی ہر قسم کا ظلم اور جبر روا رکھتے تھے۔ جنگِ عظیم میں شکست کے بعد غربت، بھوک اور طرح طرح کے مسائل نے عوام کو لینن کی قیادت میں نکولس دوم کو تخت و تاج سے محروم کرنے پر آمادہ کرلیا اور وہاں حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ لینن کا خیال تھا کہ روس کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے نظام کو بدلنا ضروری ہے اور یہی کیا گیا۔
انقلابِ روس کے اس مختصر بیان کے بعد یہاں ہم پاک و ہند کے ممتاز ادیب، نام وَر انقلابی اور مارکسی دانش وَر سجّاد ظہیر کی وہ تحریر نقل کررہے ہیں جس میں انھوں نے مشرقی اقوام اور اردو ادب پر اس انقلاب کے اثرات پر روشنی ڈالی ہے۔
سجّاد ظہیر لکھتے ہیں: "انقلابِ روس کا تمام اقوامِ مشرق پر گہرا اثر پڑا۔ دنیا کی پہلی مزدوروں اور کسانوں کی حکومت کے قیام، سرمایہ داری اور جاگیری نظام کے خاتمے اور روسی سلطنت میں محکوم ایشیائی اقوام کی آزادی نے مشرقی قوموں کی آزادی کی تحریکوں میں نیا جوش اور ولولہ پیدا کیا۔”
"ایک نیا انقلابی فلسفہ، نیا انقلابی طریقۂ کار مثالی حیثیت سے ہمارے سامنے آیا۔ ساتھ ہی ساتھ روس کی نئی حکومت نے براہِ راست اور بالواسطہ مشرق کی ان قوموں کی مدد کرنا شروع کی جو سامراجی محکومی سے آزادی حاصل کرنے کی جدوجہد کر رہی تھیں۔”
"چنانچہ ترکی، ایران، افغانستان نے سوویت حکومت کی پشت پناہی حاصل کر کے سامراجی جوئے کو اتار پھینکا۔ کمال اتاترک، رضا شاہ پہلوی، شاہ امان اللہ، چین کے قومی رہنما سن یات سین روسی انقلاب کے عظیم رہنما لینن سے ذاتی تعلقات رکھتے تھے۔”
"اقوامِ مشرق کے ان آزادی خواہ رہنماؤں کو احساس تھا کہ دنیا میں ایک ایسی طاقت وجود میں آگئی ہے جو نہ صرف یہ کہ سامراجی نہیں ہے بلکہ عالمی پیمانے پر سامراج کی مخالف اور محکوم اقوام کی آزادی کی طرف دار اور حمایتی ہے۔”
"جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے، پہلی عالمی جنگ کے خاتمے کے بعد ہی یہاں پر زبردست آزادی کی لہر اٹھی تھی۔ نان کوآپریشن اور خلافت کی تحریکوں میں لاکھوں ہندوستانیوں نے شریک ہو کر برطانوی سامراج کو چیلنج کیا تھا۔ اسی زمانے میں ہندوستان کے کئی انقلابی افغاستان سے گزر کر تاشقند پہنچ گئے تھے۔ ان میں سے اکثر روسی انقلاب اور مارکسی نظریے سے متاثر ہوئے اور انہوں نے اس کی کوشش کی کہ ہندوستان میں کمیونسٹ خیالات اور کمیونسٹ طریقۂ کار کی ترویج کی جائے۔ ہندوستان کی برطانوی حکومت نے ہندوستان میں مارکسی لٹریچر کی درآمد اور اس کی اشاعت پر سخت ترین پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ پھر بھی ہندوستان کے انقلابی غیر قانونی طریقے سے اس قسم کا لٹریچر حاصل کر لیتے تھے۔”
"ہمارے صنعتی مرکزوں کے مزدوروں کے ایک حصے، نوجوان دانش وروں اور طلبہ میں مارکسی نظریے اور فلسفے کا مطالعہ ہونے لگا تھا۔ بمبئی، کلکتہ ، لاہور، امرتسر وغیرہ میں ایسے رسالے اور ہفتہ وار نکالے جاتے جن میں مارکسی خیالات اور روس کی انقلابی حکومت کے کارناموں، عالمی کمیونسٹ تحریک کے متعلق اطلاعات اور خبریں فراہم کی جاتیں۔ گو کہ ان رسالوں کی عمر کم ہوتی تھی پھر بھی وہ اپنا کام کر جاتے تھے۔”
"اردو ادب کی ایک بہت بڑی خوش گوار خصوصیت یہ رہی ہے کہ ہماری قومی زندگی کے ہر اہم موڑ، ہماری آزادی کی جدوجہد کے ہر نئے عہد کی اس نے عکاسی کی ہے۔”
"ہندوستانی عوام کے دل کی دھڑکنیں، ان کی بلند ترین آرزوئیں، ان کے دکھ اور درد، ان کے ذہنی اور نفسیاتی پیچ و خم کی تصویریں ہمیں عہد بہ عہد اردو ادب میں مل جاتی ہیں۔”
"انقلابِ روس (نومبر1917ء) کے وقت میری عمر بہت کم تھی، لیکن لکھنؤ کے روزنامہ ‘سیارہ’ کی وہ سرخی آج تک میرے ذہن پر نقش ہے جس میں انقلاب روس کی خبر پورے صفحے پر پھیلی ہوئی، "یورپ کی لال آندھی” کے عنوان سے دی گئی تھی۔ اس روزنامے کے ایڈیٹر میرے چچا شبیر حسین قتیل مرحوم تھے۔ تھوڑے عرصے بعد "سیارہ” سے ایک بڑی ضمانت طلب کر لی گئی اور اسے اپنی اشاعت روک دینا پڑی۔ قتیل صاحب نے اس سیارہ کے آخری شمارے کو اس شعر سے شروع کیا تھا:
مرا درد بست اندر دل اگر گویم زباں سوزد
وگر دم در کشم ترسم کہ مغز استخواں سوزد
(ترجمہ: میرے دل میں آج ایسا درد ہے جس کا اگر بیاں کروں تو زبان جل اٹھے اور اگر نہ بولوں سانس اندر کھینچوں تو اس کا ڈر ہے کہ میری ہڈیاں جلنے لگیں)۔
اس شعر سے برطانوی ظلم کے خلاف ہندوستانی قوم کے غم و غصے کا اظہار ہوتا تھا۔”
"یہ امر بھی تاریخی اہمیت کا حامل ہے کہ مارکس کے شہرۂ آفاق کمیونسٹ مینی فسٹو کا پہلا اردو ترجمہ مولانا ابوالکلام آزاد کے ہفتہ وار "الہلال” میں قسط وار شائع کیا گیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ترجمہ مولانا عبدالرزاق ملیح آبادی نے کیا تھا جو اس زمانے میں الہلال کے ایڈیٹوریل اسٹاف میں کام کرتے تھے۔ مولانا ملیح آبادی (جیسا کہ بعد کو وہ کہلائے) ہمارے اس دور کے ان مفکرین اور عالموں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی تحریروں کے ذریعے سالہا سال تک اردو میں ترقی پسندی، عقلیت پسندی نیز مارکسی خیالات کی ترویج کی۔ وہ پکے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک روشن خیال شخص بھی تھے۔ اور مولانا حسرت موہانی کی طرح ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ اسلام اور کمیونزم میں کوئی تضاد نہیں ہے۔”
"عربی اور علوم دینیہ کے عالم ہونے کے علاوہ وہ ردود کے نہایت عمدہ نثر نگار اور ہمارے چوٹی کے جرنلسٹوں میں بھی تھے۔ اپنے مضامین، رسالوں اور کتابوں میں انہوں نے روسی انقلاب کے واقعات، روس کی سوویت حکومت کی پالیسیوں اور کمیونسٹ نظریات کی مسلسل بڑے سہل اور دل کش انداز میں ترویج کی۔”
"کیا اچھا ہو اگر مولانا ملیح آبادی کے اس قسم کے تمام مضامین جو ان کے اخبار ‘روزانہ ہند’ (کلکتہ) میں سالہا سال شائع ہوئے اور ان کی اس قسم کی دیگر تحریروں کا ایک مجموعہ شائع کیا جائے۔ اسی طور سے مولانا حسرت موہانی کا وہ خطبۂ صدارت بھی قابلِ دید ہوگا جو انہوں نے کانپور میں منعقد کمیونسٹ پارٹی کی پہلی کانفرنس میں پڑھا تھا۔ افسوس کہ یہ اب دست یاب نہیں ہوتا۔”
"چند سال پیشتر ‘سوویت دیس’ میں یہ خبر بھی شائع ہوئی تھی کہ انقلابِ روس کے تھوڑے ہی عرصے بعد لاہور سے لینن کی حیات پر ایک چھوٹی سی کتاب اردو میں شائع ہوئی تھی۔ یہ کتاب نہ صرف اردو میں بلکہ شاید ہندوستان میں لینن کی پہلی سوانح حیات ہے۔”
"بیسویں صدی کی تیسری اور چوتھی دہائی میں اردو میں دو شخصیتوں نے مارکسی خیالات اور انقلابی کمیونسٹ تحریک کے مختلف تاریخی اور فلسفیانہ پہلوؤں پر متعدد کتابیں لکھ کر شائع کیں۔ یہ امرتسر کے اشتراکی ادیب باری اور ٹیکارام سخن ہیں۔ باری صاحب تو اشتراکی ادیب کے نام سے ہی مشہور ہو گئے۔ ہندوستان کے اردو داں مارکسی ہمیشہ ان کے ممنون احسان رہیں گے۔ گوکہ ان میں اس قدر زیادہ سہل پسندی تھی کہ مارکسزم کے مکمل فلسفیانہ نکتوں کی پیچیدگیوں کو وہ اپنی تحریروں میں حذف کر دیتے تھے، تاہم ان کی تحریروں نے ایک بہت بڑے گروہ کو متاثر کیا اور مارکسزم کا طرف دار بنایا۔”
"غالباً اردو زبان میں سب سے ضخیم اور تاحال سب سے زیادہ مستند کتاب مارکسزم پر چودھری شیر جنگ کی ہے، جو سن 1945ء یا 1946ء میں شائع ہوئی۔ یہ کتاب کارل مارکس کے سوانح حیات اور مارکسی نظریات کے متعلق ہے، اور بڑے سائز پر پانچ سو صفحوں سے زیادہ کی ہے۔ چودھری شیر جنگ دہشت پسند انقلابیوں کے گروہ سے تعلق رکھتے تھے۔ انہیں عمر قید کی سزا ہوئی۔ اپنی طویل گرفتاری کے دوران وہ مارکسسٹ ہوگئے اور اسی زمانے میں یہ کتاب انہوں نے تحریر کی جسے اپنی رہائی کے بعد شائع کرایا۔”
"1930ء کے بعد اردو ادب پر مارکسی نظریات اور خیالات کا اثر بہت نمایاں طور سے نمودار ہونے لگا۔ 1935ء میں ‘انجمن ترقی پسند مصنفین’ کی داغ بیل ڈالی گئی۔ اسی زمانے میں اختر حسین رائے پوری نے ‘انجمن ترقیٔ اردو ہند’ کے رسالے ‘اردو’ میں ادب کے انقلابی اور ترقی پسند نظریے کے متعلق اپنا طویل مضمون شائع کیا۔”
"اردو تنقید میں مارکسی نقطۂ نظر کا آغاز اسی مضمون سے ہوتا ہے اور گو آج ہم کو اس مضمون میں بہت سی خامیاں اور کج رویاں نظر آتی ہیں لیکن یہ خامیاں راقم کی کم ہیں، وہ اس دور کے مارکسی دانش وروں کی عام خامیاں ہیں۔ بہرحال اردو ادب میں مارکسی تنقید کی اوّلیت اسی مضمون کو حاصل ہے۔ اس مضمون نے پوری ایک نسل کو متاثر کیا ہے۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کے قیام کے بعد اردو ادب پر عام طور سے مارکسی نظریات کا اثر تیزی سے پھیلا۔”
"لاہور کے رسالے ‘ادبِ لطیف’ کے ایڈیٹر کچھ عرصے کے لیے فیض احمد فیض ہوئے۔ انہوں نے بھی کئی ادبی مضامین لکھے جن میں مارکسی اثر نمایاں ہے۔ 1938ء میں سردار جعفری، مجاز اور سبطِ حسن کی ادارت میں لکھنؤ سے ماہنامہ ‘نیا ادب’ شائع ہونا شروع ہوا تو گویا ترقی پسند ادیبوں کے مارکسی گروہ کا ایک باقاعدہ مرکز بن گیا۔ مجنوں گورکھپوری اور احتشام حسین کے ابتدائی تنقیدی مضامین، جو مارکس ازم سے متاثر تھے، پہلے اسی رسالے میں شائع ہوئے۔”
"اردو کا شعری ادب تو کمیونسٹ تحریک سے متاثر تھا ہی، افسانوی ادب بھی اس تحریک سے متاثر ہوا۔ یہ تاثر سب سے واضح اور دل کش شکل میں سب سے پہلے کرشن چندر کے افسانوں میں نمایاں ہوا۔ سعادت حسن منٹو گو مارکسی نہیں تھے تاہم ان پر اور راجندر سنگھ بیدی، احمد ندیم قاسمی، عصمت چغتائی اور حیات اللہ انصاری کی نثر اور طرزِ فکر حقیقت پسندی اور انسان دوستی، آزادی خواہی کی ایک ایسی ذہنیت کو ظاہر کرتی تھیں جن پر اشتراکی فلسفۂ حیات کا اثر تھا۔”
"1942ء میں بمبئی سے اردو ہفتہ وار ‘قومی جنگ’ (جس کا نام بعد کو ‘نیا زمانہ’ ہو گیا)، شائع ہونا شروع ہوا۔ یہ اردو کا پہلا ہفتہ وار تھا جو ہندوستان میں کمیونسٹ تحریک کے قانونی ہونے کے بعد بڑے اہتمام سے شائع ہوا۔ گو یہ ایک سیاسی پرچہ تھا۔ لیکن اس کے ایڈیٹوریل بورڈ میں زیادہ تر مارکسی ادیب تھے (سردار جعفری، سبط حسن، کیفی اعظمی، ظ۔ انصاری، عبداللہ ملک، کلیم اللہ، محمد مہدی ،سجاد ظہیر وغیرہ)۔”
"اردو صحافت، اردو نثر اور اردو کی ترقی پسند ادبی تحریک کو اس ہفتہ وار نے بھی متاثر کیا۔ اسی ہفتہ وار کے ساتھ اردو کی مارکسی کتابوں کی اشاعت کے لیے بھی ایک ادارہ ‘قومی دارُ الاشاعت’ کے نام سے قائم کیا گیا۔”
"اس ادارے نے سوویت یونین کی کمیونسٹ پارٹی کی تاریخ "کمیونسٹ مینی فسٹو”، "سوشلزم” اور دیگر کئی مارکسی کلاسیکی کتابیں شائع کیں۔ ہندوستان میں مارکسی ادب کی اشاعت کا یہ سب سے بڑا ادارہ تھا جو 1958ء تک قائم رہا۔”
"تقسیمِ ہند کے بعد ہندوستان میں اردو کتابوں کی اشاعت کا کام نسبتاً دشوار ہو گیا۔ اور پاکستان میں مارکسی خیالات کی ترویج پر پابندیاں عائد ہو گئیں۔ لیکن دوسری طرف ہمارے ملک میں اور عارضی طور پر اشتراکی اثرات میں بہت بڑا اضافہ ہوا ہے۔ چنانچہ یہ امر نہایت اہم ہے کہ گزشتہ سال پاکستان میں کارل مارکس کی بنیادی کتاب ‘سرمایہ’ (داس کیپٹل) کی پہلی جلد کا اردو ترجمہ شائع ہوا ہے۔ ادھر ماسکو کے بیرونی زبانوں کے اشاعت گھر نے روسی اور اشتراکی ادب کے اردو تراجم نہایت نفاست اور خوب صورتی سے شائع کیے ہیں اور یہ کتابیں اردو کے ہنودستانی مارکیٹ میں دست یاب ہو سکتی ہیں۔”
"اب ہم اردو میں لینن کی کتابوں کے علاوہ روس کے اشتراکی ادیبوں، مسکیم گورکی شولوخوف، بورس پالی وائے، استروسکی اور روس کے کلاسیکی ادیبوں تالستائی، چنخوف، ترگنیف، دستوفسکی، لرمنتوف کے شاہ کار پڑھ سکتے ہیں۔ ان کتابوں کے ترجمے اردو ادیبوں نے کیے ہیں، لیکن وہ شائع ماسکو سے ہوئے ہیں، یقیناً اردو ادب ان سے متاثر ہورہا ہے۔”
"ہم امید کرتے ہیں کہ یہ زمانہ گزرنے پر وہ اثر جو روسی انقلاب کے زمانے سے شروع ہوتا ہے، اور جو اشتراکیت کے دن بہ دن بڑھتے ہوئے اثر کے ساتھ ساتھ وسیع تر ہوتا جا رہا ہے، اردو ادب اور اس کی نثر کو اس طرح متاثر کرے گا، کہ اس میں زیادہ انسان دوستی، زیادہ حقیقت پسندی اور زیادہ فکر اور گہرائی پیدا ہو اور ہمارے وطن کی تہذیبی زندگی کو اپنے خلوص، سچائی اور تابناکی سے مالا مال کر دے۔”
(سجّاد ظہیر کی کتاب مضامینِ سجّاد ظہیر سے انتخاب)