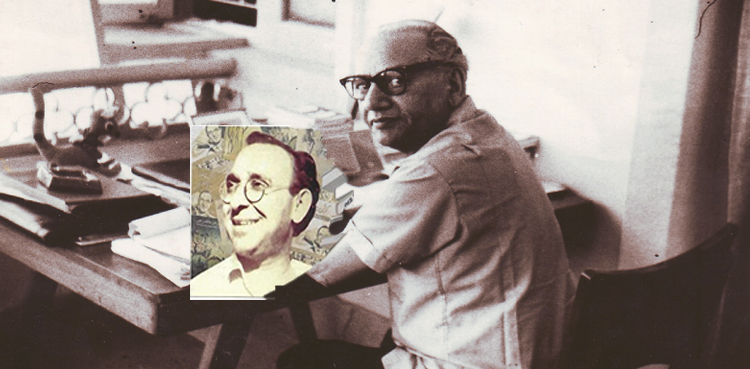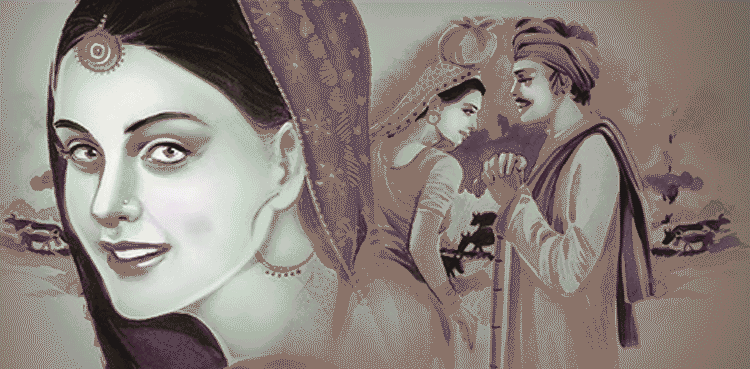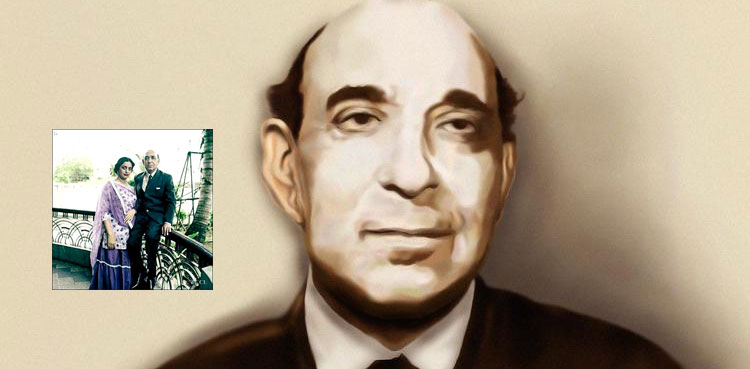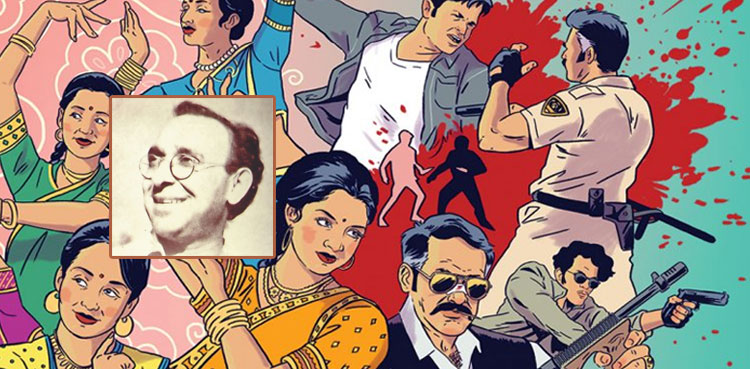جہاں ہمارا گاؤں ہے اس کے دونوں طرف پہاڑوں کے روکھے سوکھے سنگلاخی سلسلے ہیں۔ مشرقی پہاڑوں کا سلسلہ بالکل بے ریش و برودت ہے۔ اس کے اندر نمک کی کانیں ہیں۔ مغربی پہاڑی سلسلے کے چہرے پر جنڈ، بہیکڑ، املتاس اور کیکر کے درخت اگے ہوئے ہیں۔ اس کی چٹانیں سیاہ ہیں لیکن ان سیاہ چٹانوں کے اندر میٹھے پانی کے دو بڑے قیمتی چشمے ہیں، اور ان دو پہاڑی سلسلوں کے بیچ میں ایک چھوٹی سی تلہٹی پر ہمارا گاؤں آباد ہے۔
ہمارے گاؤں میں پانی بہت کم ہے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے اپنے گاؤں کے آسمان کو تپے ہوئے پایا ہے، یہاں کی زمین کو ہانپتے ہوئے دیکھا ہے اور گاؤں والوں کے محنت کرنے والے ہاتھوں اور چہروں پر ایک ایسی ترسی ہوئی بھوری چمک دیکھی ہے جو صدیوں کی ناآسودہ پیاس سے پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے گاؤں کے مکان اور آس پاس کی زمین بالکل بھوری اور خشک نظر آتی ہے۔ زمین میں باجرے کی فصل جو ہوتی ہے اس کا رنگ بھی بھورا بلکہ سیاہی مائل ہوتا ہے۔ یہی حال ہمارے گاؤں کے کسانوں اور ان کے کپڑوں کا ہے۔ صرف ہمارے گاؤں کی عورتوں کا رنگ سنہری ہے کیونکہ وہ چشمے سے پانی لاتی ہیں۔
بچپن ہی سے میری یادیں پانی کی یادیں ہیں۔ پانی کا درد اور اس کا تبسم، اس کا ملنا اور کھو جانا۔ یہ سینہ اس کے فراق کی تمہید اور اس کے وصال کی تاخیر سے گودا ہوا ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں بہت چھوٹا سا تھا دادی اماں کے ساتھ گاؤں کی تلہٹی کے نیچے بہتی ہوئی رویل ندی کے کنارے کپڑے دھونے کے لیے جایا کرتا تھا۔ دادی اماں کپڑے دھوتی تھیں میں انہیں سکھانے کے لیے ندی کے کنارے چمکتی ہوئی بھوری ریت پر ڈال دیا کرتا تھا۔ اس ندی میں پانی بہت کم تھا۔ یہ بڑی دبلی پتلی ندی تھی۔ چھریری اور آہستہ خرام جیسے ہمارے سردار پیندا خان کی لڑکی بانو۔
مجھے اس ندی کے ساتھ کھیلنے میں اتنا ہی لطف آتا تھا جتنا بانو کے ساتھ کھیلنے میں۔ دونوں کی مسکراہٹ میٹھی تھی اور مٹھاس کی قدر وہی لوگ جانتے ہیں جو میری طرح نمک کی کان میں کام کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ہماری رویل ندی سال میں صرف چھ مہینے بہتی تھی، چھ مہینے کے لیے سوکھ جاتی۔ جب چیت کا مہینہ جانے لگتا تو ندی سوکھنا شروع ہو جاتی اور جب بیساکھ ختم ہونے لگتا تو بالکل سوکھ جاتی، اور پھر اس کی تہ پر کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے نیلے پتھر رہ جاتے یا نرم نرم کیچڑ جس میں چلنے سے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ریشم کے دبیز غالیچے پر گھوم رہے ہوں۔ چند دنوں میں ہی ندی کا کیچڑ بھی سوکھ جاتا اور اس کے چہرے پر باریک درزوں اور جھریوں کا جال پھیل جاتا۔
مجھے یاد ہے پہلی بار جب میں نے ندی کو اس طرح سوکھتے ہوئے پایا تھا تو بے کل، بے چین اور پریشان ہو گیا تھا اور رات سو بھی نہ سکا تھا۔ اس رات دادی اماں مجھے بہت دیر تک گود میں لے کر عجیب عجیب کہانیاں سناتی رہیں اور ساری رات دادی اماں کی گود میں لیٹے لیٹے مجھے رویل ندی کی بہت سی پیاری باتیں یاد آنے لگیں۔ اس کا ہولے ہولے پتھروں سے ٹھمکتے ہوئے چلنا، اور پتھروں کے درمیان سے اس کا ذرا تیز ہونا اور کترا کر چلنا، جیسے کبھی کبھی بانو غصے میں گلی کے موڑ پر سے تیزی سے نکل جاتی ہے اور جہاں دو پتھر ایک دوسرے کے بہت قریب ہوئے تھے وہاں میں اور بانو باجرے کی ڈنڈیوں کی بنی ہوئی پن چکی لٹکا دیتے تھے اور گیلا آٹا پساتے تھے۔ پن چکی ندی کی آہستہ خرامی کے باوجود کیسے تیز تیز چکر لگا کر گھومتی تھی اور اب یہ ندی سوکھ گئی۔
ان سب باتوں کو یاد کر کے میں نے دادی اماں سے پوچھا:
’’دادی اماں یہ ہماری ندی کہاں چلی گئی؟‘‘
زمین کے اندر چھپ گئی۔‘‘
’’کیوں؟‘‘
’’سورج کے ڈر سے۔‘‘
’’کیوں؟ یہ سورج سے کیوں ڈرتی ہے؟ سورج تو بہت اچھا ہے۔
’’سورج ایک نہیں بیٹا، دو سورج ہیں۔ ایک تو سردیوں کا سورج ہے۔ وہ بہت اچھا اور مہربان ہوتا ہے۔ دوسرا سورج گرمیوں کا ہے۔ یہ بڑا تیز چمکیلا اور غصے والا ہوتا ہے، اور یہ دونوں باری باری ہر سال ہمارے گاؤں میں آتے ہیں۔ جب تک تو سردیوں کا سورج رہتا ہے ہماری ندی اس سے بہت خوش رہتی ہے، لیکن جب گرمیوں کا ظالم سورج آتا ہے تو ہماری ندی کے جسم سے اس کا لباس اتار نا شروع کرتا ہے۔ ہر روز کپڑے کی ایک تہ اترتی چلی جاتی ہے اور جب بیساکھی کا آخری دن آتا ہے تو ندی کے جسم پر پانی کی ایک پتلی سی چادر رہ جاتی ہے۔ اس رات کو ہماری ندی شرم کے مارے زمین پر چھپ جاتی ہے اور انتظار کرتی ہے سردیوں کے سورج کا جو اس کے لیے اگلے سال پانی کی نئی پوشاک لائے گا۔‘‘
میں نے آنکھ جھپکتے ہوئے کہا:’’سچ مچ گرمیوں کا سورج تو بہت برا ہے۔‘‘
’’لو اب سو جاؤ بیٹا۔‘‘ مگر مجھے نیند نہیں آرہی تھی۔ اس لیے میں نے ایک اور سوال پوچھا؟
’’دادی یہ ہمارے نمک کے پہاڑ کا پانی کیوں کڑوا ہے۔‘‘ ہمارے گاؤں میں بچّے پانی کے لیے بہت سوال کرتے تھے۔ پانی ان کے تخیل کو ہمیشہ اکساتا رہتا ہے۔ دوسرے گاؤں میں، جہاں پانی بہت ہوتا ہے، وہاں کے لڑکے شاید سونے کے جزیرے ڈھونڈتے ہوں گے یا پرستان کا راستہ تلاش کرتے ہوں گے لیکن ہمارے گاؤں کے بچّے ہوش سنبھالتے ہی پانی کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ اور تلہٹی پر اور پہاڑی پر اور دور دور تک پانی کو ڈھونڈنے کا کھیل کھیلتے ہیں۔ میں نے بھی اپنے بچپن میں پانی کو ڈھونڈا تھا اور نمک کے پہاڑ پر پانی کے دو تین نئے چشمے دریافت کیے تھے۔
مجھے آج تک یاد ہے میں نے کتنے چاؤ اور خوشی سے پانی کا پہلا چشمہ ڈھونڈا تھا، کس طرح کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میں نے چٹانوں کے درمیان سے جھجھکتے ہوئے پانی کو اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیوں کا سہارا دے کر باہر بلایا تھا اور جب پہلی بار اسے اوک میں لیا تو پانی میرے ہاتھ میں یوں کانپ رہا تھا جیسے کوئی گرفتار چڑیا بچّے کے ہاتھوں میں کانپتی ہے۔ پھر جب میں اسے اوک میں بھر کر اپنی زبان تک لے گیا تو مجھے یاد ہے میری کانپتی ہوئی خوشی کیسے تلخ بچھو میں تبدیل ہو گئی تھی۔ پانی نے زبان پر جاتے ہی بچھو کی طرح ڈنک مارا اور اس کے زہر نے میری روح کو کڑوا کر دیا۔ میں نے پانی تھوک دیا اور پھر کسی نئے چشمے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا، لیکن نمک کے پہاڑ پر مجھے آج تک میٹھا چشمہ نہ ملا۔ اس لیے جب ندی سوکھنے لگی تو میٹھے چشمے کی یاد نے مجھے بے چین کر دیا۔ اور میں نے دادی اماں سے پوچھا: ’’دادی ماں یہ نمک کے پہاڑ کا پانی کڑوا کیوں ہے؟‘‘
دادی اماں نے کہا۔’’یہ تو ایک دوسری کہانی ہے۔‘‘
’’تو سناؤ۔‘‘
’’نہیں اب سو جاؤ۔‘‘
میں چیخا:’’نہیں سناؤ۔‘‘
’’اچھا بابا سناتی ہوں، مگر تم اب چیخو گے نہیں۔‘‘
’’نہیں‘‘
’’اور نہ ہی بیچ بیچ میں ٹوکو گے۔‘‘
’’نہیں‘‘
’’اچھا تو سنو۔ یہ تم اس طرف نمک کی پہاڑی جو دیکھتے ہو یہ پرانے زمانے میں ایک عورت تھی جو اس پہاڑ کی بیوی تھی، جہاں آج کل میٹھے پانی کا چشمہ ہے۔‘‘
’’پھر‘‘
’’پھر ایک روز دیوؤں میں بڑی جنگ چھڑی اور یہ سامنے پہاڑ بھی جو اس عورت کا خاوند تھا، جنگ میں بھرتی ہو گیا اور بیوی کو پیچھے چھوڑ گیا اور سے کہہ گیا کہ وہ اس کے آنے تک کہیں نہ جائے، نہ کسی سے بات کرے، صرف اپنے گھر کا خیال کرے۔‘‘
’’اچھا!‘‘
’’ہاں۔ پھر کئی سال تک بیوی اپنے دیو خاوند کا انتظار کرتی رہی لیکن اس کا خاوند جنگ سے نہ لوٹا۔ آخر ایک دن اس کے گھر میں ایک سفید دیو آیا اور اس پر عاشق ہو گیا۔‘‘
’’عاشق کیا ہوتا ہے۔‘‘
دادی اماں رک گئیں، بولیں: تو نے پھر ٹوکا۔’’میں نے دل میں سوچا: دادی اماں اگر خفا ہو گئیں تو باقی کہانی سننے کو نہیں ملے گی اور کہانی اب دل چسپ ہوتی جا رہی ہے اس لیے چپکے سے سن لینا چاہیے، عاشق کا مطلب بعد میں پوچھ لیں گے۔ اس لیے میں نے جلدی سے سوچ کر دادی ماں سے کہا۔’’اچھا اچھا، دادی اماں آگے سناؤ، اب نہیں ٹوکوں گا۔‘‘
دادی اماں رکھائی سے اس طرح خفا ہو کے بولیں جیسے انہیں کہانی کا آگے آنے والا حصہ پسند نہیں ہے۔ کہنے لگیں:’’ہونا کیا تھا، مغربی پہاڑی کی بیوی بے وفا نکلی۔ جب اسے سفید دیو نے جھوٹ موٹ یقین دلا دیا کہ اس کا پہلا خاوند دیوؤں کی جنگ میں مارا گیا ہے تو اس نے سفید دیو سے شادی کر لی۔‘‘
’’دیوؤں کی جنگ کیوں ہوتی تھی؟’’میرے منہ سے بے اختیا ر نکل گیا۔‘‘
’’تو نے پھر ٹوکا۔‘‘دادی اماں بہت خفا ہو کے بولیں،’’چل اب آگے نہیں سناؤں گی۔‘‘ نہیں دادی اماں میری اچھی دادی اماں اچھا اب بالکل نہیں ٹوکوں گا۔‘‘میں نے منت سماجت کرتے ہوئے کہا۔
’’پھر؟‘‘
’’پھر ایک دن بہت سالوں کے بعد ایک بوڑھا دیو اس وادی میں آیا۔ یہ اسی عورت کا پہلا خاوند تھا۔ جب اس نے اپنی بیوی کو سفید دیو کے ساتھ دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا اور اس نے کلہاڑا لے کر سفید دیو اور اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ جب سے ان دونوں دیوؤں کو بڑے پیر کی بد دعا ملی ہے اور یہ لوگ سل پتھر ہو گئے۔ سامنے والے پہاڑ کا پانی اس لیے میٹھا ہے کیونکہ اسے اپنی بیوی سے سچی محبت تھی۔ اس کے مقابل پہاڑ کا پانی کھارا ہے اور اس میں نمک ہے کیونکہ وہ عورت ہے اور اپنی بے وفائی پر ہر وقت روتی رہتی ہے۔ اور جب اس کے آنسو خشک ہوجاتے ہیں تو نمک کے ڈلے بن جاتے ہیں، جنہیں ہر روز تمہارا باپ پہاڑ کے اندر کھود کے نکالتا ہے۔‘‘
’’پھر؟‘‘
’’پھر کہانی ختم۔‘‘
کہانی ختم ہو گئی اور میں بھول گیا کہ میں نے کیا سوال کیا تھا۔ مجھے کیا جواب ملا۔ میں نے کہانی سن لی، اطمینان کا سانس لیا اور پلک جھپکتے ہی سو گیا۔ سوتے سوتے میری آنکھوں کے سامنے نمک کی کان کا منظر آیا، جہاں میرے ابا کام کرتے تھے، جہاں جوان ہو کر مجھے کام کرنا پڑا اور جہاں پہلی بار میں اپنی اماں کے ساتھ اپنے ابا کا کھانا لے کر گیا تھا۔ افوہ!کتنی بڑی کان تھی وہ چاروں طرف نمک کے پہاڑ نمک کے ستون، نمک کے آئینے نمک کی دیواروں میں لگے ہوئے تھے۔ ایک جگہ نمک کی آبی جھیل تھی جس کے چاروں طرف نیلگوں دیواریں تھیں اور چھت بھی نمک کی تھی جس سے قطرہ قطرہ کر کے نمک کا پانی رستا تھا اور نیچے گر کر جھیل بن گیا تھا اور یکایک مجھے خیال آیا یہ اس عورت کے آنسو ہیں جو بڑے پیر کی بد دعا سے نمک کا پہاڑ بن چکی ہے۔
میرے ابا اس جھیل کو دیکھ کر بولے:’’یہاں اس قدر پانی ہے پھر بھی پانی کہیں نہیں ملتا۔ دن بھر نمک کی کان میں کام کرتے کرتے سارے جسم پر نمک کی پتلی سی جھلی چڑھ جاتی ہے جسے کھرچو تو نمک چورا چورا ہو کر گرنے لگتا ہے۔ اس وقت کس قدر وحشت ہوتی ہے۔ جی چاہتا ہے کہیں میٹھے پانی کی جھیل ہو اور آدمی اس میں غوطے لگاتا جائے۔‘‘
’’پانی !پانی!
پانی سارے گاؤں میں کہیں نہیں تھا۔ پانی نمک کے پہاڑ پر بھی نہیں تھا۔ پانی تھا تو سامنے پہاڑ پر جس نے محبت میں بے وفائی نہیں کی تھی۔ یا پانی پھر رویل ندی میں تھا۔ لیکن یہ ندی بھی چھ مہینے غائب رہتی تھی اور پھر آخر ایک دن یہ بالکل غائب ہو گئی اور آج تک اس کے نیلے پتھر اور سوکھی ریت اور اس کے کنارے کنارے چلنے والی عورتوں کے نااُمید قدم اس کی راہ تکتے ہیں۔ لیکن یہ میرے بچپن کی کہانی نہیں ہے، یہ میرے لڑکپن کی کہانی ہے۔ جب ہمارے گاؤں سے بہت دور ان پہاڑی سلسلوں کے دوسری طرف سیکڑوں میل لمبی جاگیر کے مالک راجہ اکبر علی خان نے ہمارے دیہات والوں کی مرضی کے خلاف رویل ندی کا بہاؤ موڑ کر اپنی جاگیر کی طرف کرلیا اور ہماری تلہٹی کو اور آس پاس کے بہت سارے علاقے کو سوکھا، بنجر اور ویران کر دیا۔ اس وقت ندی کے کنارے ہمارا گاؤں اور اس وادی کے اور دوسرے بہت سے گاؤں پریشان ہو گئے۔ اس طرح ہمارے لئے رویل ندی مر گئی اور اس کا پانی بھی مر گیا اور ہمارے لئے ایک تلخ یاد چھوڑ گیا۔
مجھے یاد ہے اس وقت گاؤں والوں نے دوسرے گاؤں والوں سے مل کر سرکار سے اپنی کھوئی ہوئی ندی مانگی تھی کیونکہ ندی تو گھر کی عورت کی طرح ہے۔ وہ گھر میں پانی دیتی ہے، کھیتوں میں کام کرتی ہے، ہمارے کپڑے دھوتی ہے، جسم کو صاف رکھتی ہے۔ ندی کے گیت اس کے بچے ہیں جنہیں وہ لوری دیتے ہوئے، تھپکتے ہوئے مغرب کے جھولے کی طرف لے جاتی ہے۔ پانی کے بغیر ہمارا گاؤں بالکل ایسا ہے جیسے گھر عورت کے بغیر گاؤں والوں کو بالکل ایسا معلوم ہوا جیسے کسی نے ان کے گھر سے ان کی لڑکی اغوا کر لی ہو۔ وہی غم، وہی غصہ تھا، وہی تیور تھے، وہی مرنے مارنے کے انداز تھے۔ لیکن راجہ اکبرعلی خاں چکوال کے علاقے کا سب سے بڑا زمیندار تھا۔ حکومت کے افسروں کے ساتھ اس کا گہرا اثر و رسوخ تھا۔ نمک کی کان کا ٹھیکہ بھی اس کے پاس تھا۔
نتیجہ یہ ہوا کہ گاؤں والوں کو ان کی ندی واپس نہ ملی، الٹا ہمارے بہت سے گاؤں والے، جو نمک کی کان میں کام کرتے تھے، باہر نکال دیے گئے۔ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے اپنے گاؤں کے اغوا شدہ پانی کو واپس بلانے کی جرآت کی تھی۔ مجھے یاد ہے اس روز ابا کانپتے کانپتے گھر آئے تھے۔ ان کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا اور بار بار اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہتے: توبہ توبہ! کیسی غلطی ہوئی۔ وہ تو اللہ کا کام تھا کہ میں بچ گیا ورنہ راجہ صاحب مجھے نکال دیتے، میں تو اب کبھی راجہ کے خلاف عرضی نہ دوں، چاہے وہ پانی کیا میری لڑکی ہی کیوں نہ اغوا کر کے لے جائیں۔ توبہ توبہ!
اور یہ بھی سچ ہے کہ ہمارے گاؤں میں پانی کی عزت لڑکی کی طرح بیش قیمت ہے۔ پانی جو زندگی دیتا ہے۔ پانی جو رگوں میں خون بن کر دوڑتا ہے۔ پانی، جو منہ دھونے کو نہیں ملتا۔ پانی، جس کے نہ ہونے سے ہمارے کپڑے بھورے اور میلے رہتے ہیں، سر میں جوئیں، جسم پر پسینے کی دھاریاں اور روح پر نمک جما رہتا ہے۔ یہ پانی تو سونے سے زیادہ قیمتی ہے اور لڑکی سے زیادہ حسین۔ اس کی قدر اور قیمت ہمارے گاؤں والوں سے پوچھیے جن کی زندگی پانی کے لیے لڑتے جھگڑتے گزرتی ہے۔ ایک دفعہ سامنے کے پہاڑ کے میٹھے چشمے سے پانی لانے کے لیے سرور خاں کی بیوی سیداں اور ایوب خاں کی بیوی عائشاں دونوں آپس میں لڑ پڑی تھیں حالانکہ دونوں اتنی گہری سہیلیاں تھیں کہ ہر وقت اکٹھی رہتیں، گھر بھی ان کے ساتھ ساتھ تھے۔ چشمے پر بھی پانی اکٹھے ہی لینے جاتی تھیں۔پہلے ایک پھر دوسری پانی بھرتی۔ باری باری وہ دونوں ایک دوسرے کا گھڑا اٹھا کے سر پر رکھتیں اور پھر باتیں کرتی ہوئی واپس چل پڑتیں۔ لیکن آج نہ جانے کیا ہوا، آج جانے دونوں کو کیا جلدی تھی۔ ایک کہتی پہلے پانی میں بھروں گی، دوسری کہنے لگی نہیں میں بھروں گی۔ شاید انہیں غصہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں تھا۔ شاید غصہ انہیں اس لیے تھا کہ یہاں میٹھے پانی کا ایک ہی چشمہ تھا جہاں ندی کے سوکھ جانے کے بعد دور سے دوسرے لوگ پانی لینے کے لیے آتے تھے۔ منہ اندھیرے ہی عورتیں گھڑا لے کے چل پڑتیں۔ جب یہاں پہنچتیں تو لمبی لائن پہلے سے موجود ہوتی یا چشمے کے منہ سے ایک ایسی پتلی سی دھار کو نکلتے دیکھتیں جو آدھے گھنٹے میں مشکل سے ایک گھڑا بھرتی تھی۔ اور تین کوس کا آنا جانا قیامت سے کم نہ تھا۔ لڑائی کی وجہ کچھ بھی ہو اصلی لڑائی پانی کی تھی۔ دونوں عورتوں نے دیکھتے دیکھتے ایک دوسرے کے چہرے نوچ لیے، گھڑے توڑ دیے، کپڑے پھاڑ ڈالے اور پھر روتی ہوئی اپنے اپنے گھروں کو گئیں۔ تب سیداں نے سرور خاں کو بھڑکایا اور عائشاں نے ایوب خاں کو۔ دونو ں خاوند غصے سے بیتاب ہو کے کلہاڑیاں لے کے باہر نکل پڑے اور پیشتر اس کے کہ لوگ آکے بیچ بچاؤ کریں دونوں نے کلہاڑیوں سے ایک دوسرے کو ختم کر دیا۔ شام ہوتے ہوتے دونوں ہمسایوں کا جنازہ نکل گیا۔
ہمارے گاؤں کے قبرستان کی بہت سی قبریں پانی نے بنائی ہیں۔ میرے لڑکپن کے زمانے میں جب دو قتل ہوئے اس وقت سامنے کے پہاڑ پر ایک ہی میٹھے پانی کا چشمہ تھا لیکن بعد میں جب میں اور بڑا ہوا تو یہاں ایک اور چشمہ بھی نکل آیا۔ اس نئے چشمے کی داستان بھی بڑی عجیب ہے۔ یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب ہمارے پوٹھوہار میں سخت کال پڑا تھا اور گرمی کی وجہ سے علاقے کے سارے ندی نالے اور کنویں سوکھ گئے تھے۔ صرف کہیں کہیں ان چشموں میں پانی رہ گیا تھا۔ ان دنوں ہمارے گھروں میں عورتیں رات کے دو بجے ہی اٹھ کے چل دیتیں اور چشمے کے نیچے ہمیشہ گھڑوں کی ایک لمبی قطار جس میں سے پیاس سے بلکتے ہوئے بچوں کی صدا آتی تھی۔
اس زمانے میں بڑے بڑے لوگ نیکی اور خدائی سے منحرف ہو گئے اور ان لوگوں میں سب سے برا کام ذیلدار ملک خاں نے کیا۔ اس نے تھانیدار فضل علی سے مل کے اس چشمے پر پولیس کا پہرہ لگا دیا اور پھر تحصیل دار غلام نبی سے مل کے چشمے کے ارد گرد کی ساری زمین خرید کر راتوں رات اس پر ایک چاردیواری باندھ دی اور چار دیواری کے باہر تالا لگا دیا۔ اب اس چشمے سے کوئی آدمی بلا اجازت پانی نہ لے سکتا تھا کیونکہ اب یہ چشمہ ذیلدارکی ملکیت تھا اور اس نے چشمے سے پانی لے جانے والے گھڑوں پر اپنا ٹیکس رکھ دیا۔ ایک گھڑے پر ایک آنہ، دو گھڑوں پر دو آنے۔ تب سارے گاؤں میں ظلم کے خلاف شور مچ گیا۔ لیکن پولیس سردار ذیلدار ملک خاں کی حمایت میں تھی، قانون بھی اس کی طرف تھا اور جدھر قانون تھا پانی بھی ادھر تھا۔ اس لیے گاؤں کے سارے جوان اور بڈھے اور بچّے جمع ہو کے میرے ابا کے پاس آئے اور بولے؟’’چچا خدا بخش اب تم ہی ہمیں اس مصیبت سے نجات دلوا سکتے ہو۔‘‘
’’وہ کیسے ؟‘‘ میرے ابا نے حیران ہو کے سوال پوچھا۔ سفید ریش بڈھے حاکم خاں نے کہا ’’یاد ہے یہ میٹھے پانی کا چشمہ، جواب ذیلدار ملک خاں کا ہو گیا، یہ چشمہ بھی تم نے دریافت کیا تھا۔ کیا تم دوسرا چشمہ نہیں ڈھونڈ سکتے؟ آخر اس پہاڑ کے اندر، اس کے سینے میں اور بھی تو کہیں میٹھا پانی ہو گا جو انسان کو آب حیات بخش سکتا ہے۔ خدا بخش تم ہم سب سے قابل ہو۔ اپنی عقل دوڑاؤ ہم تمہارے ساتھ مرنے مارنے کو تیار ہیں۔ ہمارے گاؤں میں پانی نہیں ہے اور اب پانی چاہیے۔‘‘
میرا باپ چارپائی پر اکڑوں بیٹھا تھا۔ اسی وقت اللہ کا نام لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ سارا گاؤں اس کے ساتھ تھا۔ پہاڑ پر چڑھائی تھی اور تلاش پانی کی تھی۔
ایسے ہرجائی کی تلاش کے لیے ایک تیشہ نہیں ایک آئینہ چاہیے جس کے سامنے پہاڑ کا دل اس طرح ہو جیسے ایک کھلی کتاب۔ آخر میرے گاؤں والوں نے کچھ سمجھ کر میرے باپ کو اس کام کے لیے چنا تھا۔ اس روز ہم دن بھر اس بلند و بالا پہاڑ کی خاک چھانتے رہے۔ ہم نے کہاں کہاں اس پانی کو تلاش نہیں کیا: بیریوں کی گھنی جھاڑیوں میں، چٹانوں کی گہری درزوں میں، سیاہ ڈراؤنی کھوؤں میں، جنگلی جانوروں کے بھٹ میں۔ پانی کی تلاش میں ہم نے سارے پرانے چشمے کھدوائے لیکن ان کا کھودنا ایسے ہی تھا جیسے آدمی زندگی کی تلاش میں قبریں کھود ڈالے۔ پانی کہیں نہیں ملا۔ ایک چور کی طرح اس نے جگہ جگہ اپنے چھوٹے سراغ چھوڑے لیکن آخر کو وہ ہمیشہ ہمیں جل دے کر کہیں غائب ہو جاتا تھا۔ جانے فطرت کے کس کونے میں بیٹھا اپنے چاہنے والوں پر ہنس رہا تھا۔ لیکن گاؤں والوں نے آس نہیں چھوڑی۔ وہ سارا دن میرے بابا کے پیچھے پیچھے پانی کی کھوج کرتے رہے۔ آخر جب شام ہونے لگی تو میرے ابا نے پسینہ پونچھ کر ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کے ادھر نظر دوڑائی جدھر سورج غروب ہو رہا تھا۔ یکایک انہیں غروب ہوتے ہوئے سورج کی روشنی میں چٹانوں کی ایک گہری درز میں فرن کا سبز ہ نظر آیا اور کہتے ہیں جہاں فرن کا سبزہ ہوتا ہے وہاں پانی ضرور ہوتا ہے۔ فرن پانی کا جھنڈا ہے اور پانی ایک گھومنے والی قوم ہے۔ پانی جہاں جاتا ہے اپنا جھنڈا ساتھ لے جاتا ہے۔
ایک چیخ مار کر جلدی سے میرے ابا اس طرف لپکے جہاں فرن کا سبزہ اگا تھا۔ گاؤں والے ان کے پیچھے پیچھے بھاگے۔ جلدی جلدی میرے ابا نے اپنے ناخنوں ہی سے زمین کو کریدنا شروع کر دیا۔ زمین، جو اوپر سے سخت تھی، نیچے سے نرم ہوتی گئی گیلی ہوتی گئی۔ آخر میں زور سے پانی کی ایک دھار اوپر آئی اور سیکڑوں سوکھے ہوئے گلوں سے مسرت کی آواز نکلی:
’’پانی! پانی۔‘‘
ابا نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اوک میں پانی بھرا۔ ساری نگاہیں ابا کے چہرے پر تھیں، سیکڑوں دل دھڑک رہے تھے۔: یااللہ پانی میٹھا ہو، یااللہ پانی میٹھا ہو، یااللہ پانی میٹھا ہو۔؎
ابا نے پانی چکھا۔’’پانی میٹھا ہے۔‘‘ابا نے خوشی سے کہا۔ گاؤں والے زور سے چلائے :’’پانی میٹھا ہے!‘‘ساری وادی میں آوازیں گونج اٹھیں:’’میٹھا پانی مل گیا، پانی میٹھا ہے!‘‘
ساری وادی میں ڈھول بجنے لگے۔ عورتیں گانے لگیں، جوان ناچنے لگے، بچے شور مچانے لگے۔ گاؤں والوں نے جلدی سے چشمے کو کھود کر اپنے گھیرے میں لے لیا۔ اب چشمہ ان کے بیچ میں تھا اور وہ اس کے چاروں طرف تھے اور وہ اسے مڑ مڑ کر اس طرح محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے جیسے ماں اپنے نوزائیدہ بچے کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ وہ رات مجھے کبھی نہیں بھولے گی۔ اس رات کوئی آدمی گاؤں میں واپس نہیں گیا۔ اس رات سارے گاؤں نے چشمے کے کنارے جشن منایا۔ اس رات تاروں کی گود میں بھوری بیریوں کے سائے میں ماؤں نے چولہے سلگائے، بچوں کو تھپک تھپک کے سلایا، اس رات کنواریوں نے لہک لہک کر گیت گائے۔ ایسے گیت جو پانی کی طرح نرمل اور سندر تھے، جن میں جنگلی جھرنوں کا سا حسن اور آبشاروں کی سی روانی تھی۔ اس رات ساری عورتیں خوشی سے بے قرار تھیں، سارے بیج تخلیق سے بے قرار ہو کر پھوٹ پڑے تھے۔
ایسی رات ہمارے گاؤں میں کب آئی تھی جب ابا خدا بخش نے پانی ڈھونڈ نکالا تھا۔ پانی جو انسان کے ہاتھوں کی محنت تھا،اس کے دل کی محبت تھا۔آج پانی ہمارے ہاں اس طرح آیا تھا جیسے بارات ڈولی لے کر آ تی ہے۔ وہ نیا چشمہ ہمارے درمیان آج اس طرح ہولے ہولے شرمیلے انداز میں چل رہا تھا جیسے نئی دلہن جھجک جھجک کر اجنبی آنگن میں پاؤں رکھتی ہے، اس رات میرے ایک ہاتھ میں پانی تھا، دوسرے ہاتھ میں بانو کا ہاتھ تھا اور آسماں پر ستارے تھے۔ اس نئے چشمے کے ساتھ میری جوانی کی بہترین یادیں وابستہ ہیں۔ اس چشمے کے کنارے میں نے بانو سے محبت کی۔ بانو جس کا حسن پانی کی طرح نایاب تھا، جسے دیکھ کر ہمیشہ یہ خیال آتا تھا کہ جانے اس زمین کی گود میں کتنے ہی میٹھے چشمے نہاں ہیں، کتنی حسین یادیں منجمد ہیں، موسم گرما کے کتنے ہی شوخ چمکتے ہوئے پھول، خزاؤں کے سنہری پتے، زمستان کی پاکیزہ برف، بانو کی محبت بھی کتنی خاموش اور چپ چاپ تھی، زمین کے نیچے بہنے والے پانی کی طرح۔
وہ رات کے اندھیرے میں یا فجر سے بہت پہلے اس چشمے کے کنارے آتی تھی، جب یہاں اور کوئی نہ ہوتا میرے سوا۔ وہ گھڑے کو چشمے کی دھار کے نیچے رکھ دیتی۔ پانی گھڑے سے باتیں کرنے لگتا اور میں بانو سے۔ مجھے وہ دن یاد آتا جب میں نے دادی اماں سے پوچھا تھا:’’دادی اماں عاشق کس کو کہتے ہیں؟‘‘
اور پھر اس چشمے کے کنارے مجھے وہ رات بھی یاد ہے جب میں کان میں کام کرتا تھا اور دن بھر تھک کے گھر لوٹتا تھا اور اس تھکن سے چور ہو کر سو جاتا تھا، صبح ہی آنکھ کھلتی تھی۔ کئی دنوں سے میں بانو سے چشمے پر ملنے نہ گیا تھا مگر کوئی بے قراری نہ تھی۔ وہ ساتھ کے گھر میں تو رہتی تھی۔ انہی دنوں میں اس کے چچا کا لڑکا غضنفر بھی آیا اور چلا بھی گیا لیکن مجھے اس سے ملنے کی بھی فرصت نہ ملی کیونکہ کان میں نیا نیا ملازم ہوا تھا، کام سیکھنے کا بہت شوق تھا اور یہ تو ہر شخص کو معلوم ہے کہ نمک کی کان میں جا کے ہر شخص نمک ہو جاتا ہے۔
ایک رات بانو نے مجھے کہا کہ رات کے دو بجے چشمے پر اس سے ملوں۔ میں نے کہا:’’میں بہت تھکا ہوا ہوں۔‘‘
وہ بولی :’’نہیں ضروری کام ہے، آنا ہو گا۔‘‘چنانچہ میں گیا۔
دو بجے کے وقت آدھی رات میں چشمے پر کوئی نہیں تھا، ہم دونوں کے سوا۔ میں نے اس سے پوچھا:’’کیا بات ہے؟‘‘
وہ بولی،’’میں گاؤں چھوڑ کے جا رہی ہوں۔‘‘
میرا دل دھک سے رہ گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے چشمہ چلتا چلتا رک گیا۔ میرے گلے سے آواز نکلی:’’کیوں؟‘‘
’’میری شادی طے ہو گئی ہے۔‘‘
کس سے؟ چاچا کے لڑکے کے ساتھ۔ وہ چکوال میں ہے۔ صوبیدار ہے۔
اور تم جا رہی ہو! میں نے تلخی سے پوچھا۔ ہاں وہ چپ ہوگئی۔ میں بھی چپ ہو گیا۔ سوچ رہا تھا اسے ابھی جان سے نہ مار دوں یا شادی کی رات قتل کروں۔ تھوڑی دیر رک کے بانو پھر بولی:’’سنا ہے چکوال میں پانی بہت ہوتا ہے، سنا ہے وہاں بڑے بڑے نل ہوتے ہیں جن سے جب چاہو ٹوٹی گھما کے پانی نکال لو۔ اس کی آواز خوشی کے مارے کانپ رہی تھی۔ وہ شاید اور بھی کچھ کہتی لیکن شاید میری آزردگی کا خیال کر کے چپ ہو گئی۔
میں نے اس کے بالکل قریب آکر اسے دونوں شانوں سے پکڑ لیا اور غور سے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا۔ اس نے ایک لمحہ میری طرف دیکھ کر آنکھیں جھکا لیں۔ اس کی نگاہوں میں میری محبت سے انکار نہیں تھا بلکہ پانی کا اقرار تھا۔ میں نے آہستہ سے اس کے شانے چھوڑ دیے اور الگ ہو کے کھڑا ہو گیا۔ یکایک مجھے محسوس ہوا کہ محبت سچائی خلوص اور جذبے کی گہرائی کے ساتھ ساتھ تھوڑا پانی بھی مانگتی ہے۔ بانو کی جھکی ہوئی نگاہوں میں اک ایسے جانگسل شکایت کا گریز تھا جیسے وہ کہہ رہی ہو: جانتے ہو ہمارے گاؤں میں کہیں پانی نہیں ملتا۔ یہاں میں دو دو مہینے نہا نہیں سکتی۔ مجھے اپنے آپ سے اپنے جسم سے نفرت ہوگئی ہے۔ بانو چپ چپ زمین پر چشمے کے کنارے بیٹھ گئی۔ میں اس تاریکی میں بھی اس کی آنکھوں کے اندر اس کی محبت کے خواب کو دیکھ سکتا تھا جو گندے بدبو دار جسموں پسوؤں، جوؤں اور کھٹملوں کی ماری غلیظ چیتھڑوں میں لپٹی ہوئی محبت نہ تھی۔ اس محبت سے نہائے ہوئے جسموں، دھلے ہوئے کپڑوں اور نئے لباس کی مہک آتی تھی۔ میں بالکل مجبور اور بے بس ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ رات کے دو بجے۔ بانو اور میں۔ دونوں چپ چاپ کبھی ایسا سناٹا جیسے ساری دنیا کالی ہے، کبھی ایسی خاموشی جیسے سارے آنسو سو گئے ہیں۔ چشمے کے کنارے بیٹھی ہوئی بانو آہستہ آہستہ گھڑے میں پانی بھرتی رہی۔ آہستہ آہستہ پانی گھڑے میں گرتا ہوا بانو سے باتیں کرتا رہا۔ اس سے کچھ کہتا رہا، مجھ سے کچھ کہتا رہا۔ پانی کی باتیں انسان کی بہترین باتیں ہیں۔
بانو چلی گئی۔ جب بانو چلی گئی تو میرے ذہن میں بچپن کی وہ کہانی آئی جب محبت روئی تھی اور آنسو نمک کے ڈلے بن گئے تھے۔ اس وقت میری آنکھ میں آنسو بھی نہ تھا لیکن میرے دل کے اندر نمک کے کتنے بڑے ڈلے اکٹھے ہوگئے تھے! میرے دل کے اندر نمک کی ایک پوری کان موجود تھی۔ نمک کی دیواریں، ستون، غار اور کھارے پانی کی ایک پوری جھیل۔ میرے دل اور دماغ اور احساسات پر نمک کی ایک پتلی سی جھلی چڑھ گئی تھی اور مجھے یقین ہوچلا تھا کہ اگر میں اپنے جسم کو کہیں سے بھی کھرچوں گا تو آنسو ڈھلک کر بہہ نکلیں گے، اس لیے میں چپ چاپ بیٹھا رہا اور جب وہ میری طرف دیکھ کر ڈھلوان پر مڑ گئی اس وقت بھی میں چپ چپ بیٹھا رہا کیونکہ میرے پاس پانی نہیں تھا۔ اور بانو پانی کے پاس جارہی تھی۔
جس رات بانو کا بیاہ غضنفر سے ہوا اس رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ ہماری کھوئی ہوئی ندی ہمیں واپس مل گئی ہے اور نمک کے پہاڑ پر میٹھے پانی کے چشمے ابل رہے ہیں اور ہمارے گاؤں کے مرکز میں ایک بہت بڑا درخت کھڑا ہے۔ یہ درخت سارے کا سارا پانی کا ہے، اس کی جڑیں، شاخیں، پھل، پھول، پتیاں سب پانی کی ہیں اور اس درخت کی شاخوں سے، پتوں سے پانی بہہ رہا ہے اور یہ پانی ہمارے گاؤں کی بنجر زمین کو سیراب کر رہا ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ کسان ہل جوت رہے ہیں، عورتیں کپڑے دھو رہی ہیں، کان کن نہا رہے ہیں اور بچے پھولوں کے ہار لیے پانی کے درخت کے گرد ناچ رہے ہیں اور بانو صاف ستھرے کپڑے پہنے میرے کندھے سے لگی مجھ سے کہہ رہی ہے: اب ہمارے گاؤں میں پانی کا درخت اُگ آیا ہے۔ اب میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ یہ بڑا عجیب خواب تھا لیکن میں نے جب اپنے باپ کو سنایا تو وہ مارے ڈر کے کانپنے لگے اور بولے: ’’تم نے یہ خواب میرے سوا کسی دوسرے کو تو نہیں سنایا‘‘میں نے کہا :’’نہیں ابا، مگر آپ ڈر کیوں گئے ہیں۔ یہ تو ایک خواب تھا۔
وہ بولے:’’ارے خواب تو ہے مگر یہ ایک سرخ خواب ہے۔‘‘میں نے ہنس کر کہا:’’نہیں ابا جو درخت میں نے خواب میں دیکھا وہ سرخ نہیں تھا۔ اس کا رنگ تو بالکل جیسے پانی کا ہوتا ہے۔ وہ پانی کا درخت تھا۔ اس کا تنا، شاخیں، پتے سب پانی کے تھے۔ ہاں اس درخت پر پھلوں کی جگہ کٹ گلاس کی چمکتی ہوئی صراحیاں لٹکی تھیں اور ان میں پانی بچوں کی ہنسی کی طرح چمکتا تھا اور فواروں کی طرح اونچا جا کے گرتا تھا۔‘‘ وہ بولے۔’’کچھ بھی ہو یہ بڑا خطرناک سپنا ہے۔ اگر پولیس نے کہیں سن لیا یا تم نے کسی سے اس کا ذکر کر دیا تو وہ تمہیں اس طرح پکڑکے لے جائیں گے جس طرح وہاں مزدوروں کو پکڑ کے لے گئے تھے جنہوں نے ہمارے گاؤں کی ندی کو واپس لانا چاہا تھا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اس خواب کا ذکر کسی سے نہ کرو۔ اسے بھول جاؤ کیونکہ اس خواب کا چرچا کر کے اس سے کچھ نہ ہو گا، سوکھی ندی ہمیشہ سوکھی رہے گی اور پیاسے سدا پیاسے رہیں گے۔‘‘مجھے اپنے اباکے لہجے کی حسرت آج تک یاد ہے۔مجھے یہ بھی یاد ہے کہ شروع شروع میں اس کا ذکر میں نے کسی سے نہیں کیا لیکن جب چند مزدور ساتھیوں سے اپنے خواب کا ذکر کیا تو وہ میرا خواب دیکھ کر ڈرنے کی بجائے ہنسنے لگے اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے تو انہوں نے کہا:’’بھلا اس میں ڈرانے کی کیا بات ہے۔ یہ خواب تو بہت اچھا ہے اور یہ ان کی کان میں ہر ایک دیکھ چکا ہے۔‘‘
’’کیا سچ کہتے ہو! وہی پانی کا درخت؟‘‘
’’ہاں ہاں۔ وہی پانی کا درخت گاؤں میں، ایک ٹھنڈا میٹھا پانی کا چشمہ ہر نمک کی کان میں!‘‘
’’گھبراؤ نہیں، ایک دن یہ خواب ضرور پورا ہوگا۔‘‘
پہلے مجھے ان کی باتوں کا یقین نہیں آیا۔ لیکن اپنے ساتھیوں کے ساتھ کام کرتے کرتے اب مجھے یقین ہو چلا ہے کہ ہمارا خواب ضرور پورا ہوگا۔ایک دن ہمارے گاؤں میں پانی کا درخت ضرور اگے گا۔ اور جو جام خالی ہیں وہ بھر جائیں گے اور جو کپڑے میلے ہیں وہ دھل جائیں گے اور جو دل ترسے ہوئے ہیں وہ کھل جائیں گے اور ساری زمینیں اور ساری محبتیں اور سارے ویرانے اور سارے صحرا شاداب ہو جائیں گے۔
(کرشن چندر کا افسانہ)