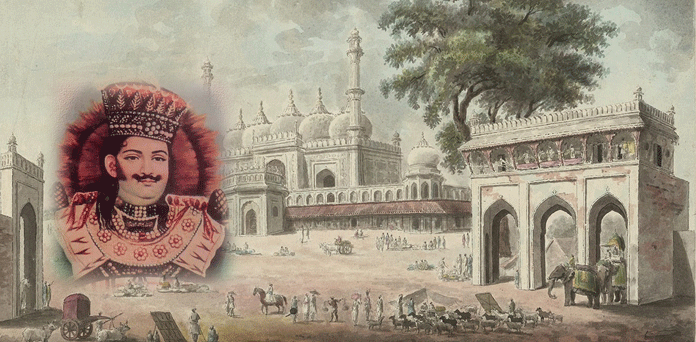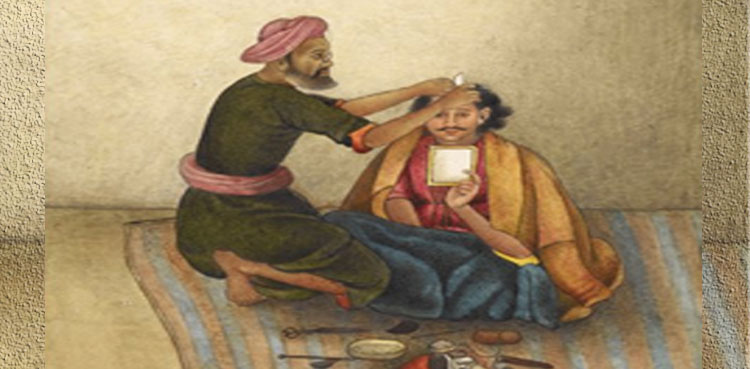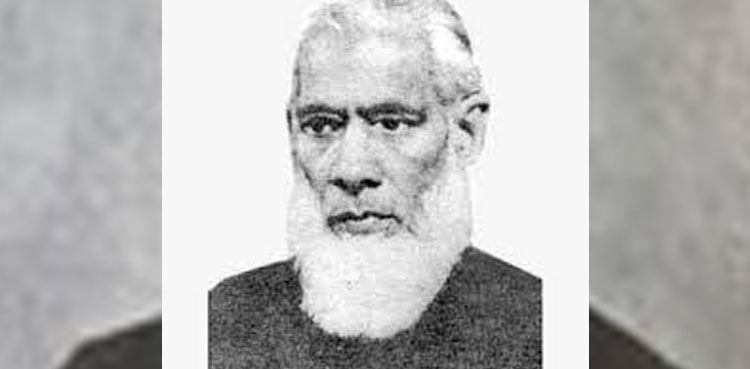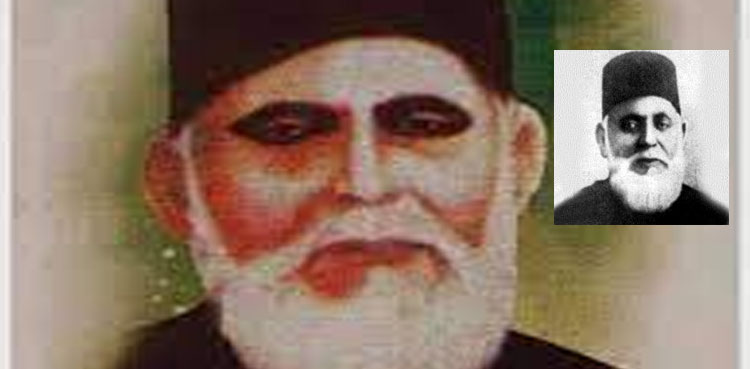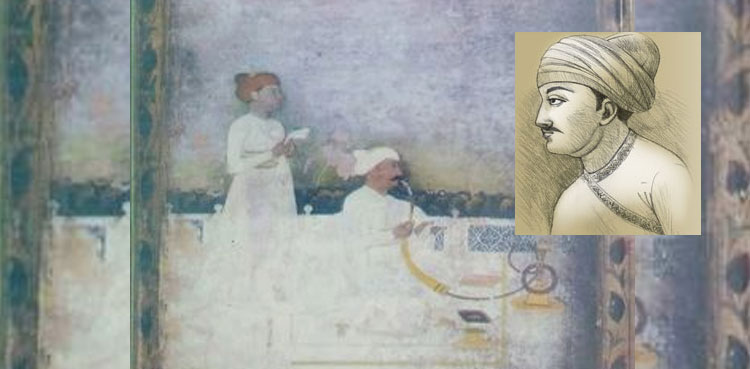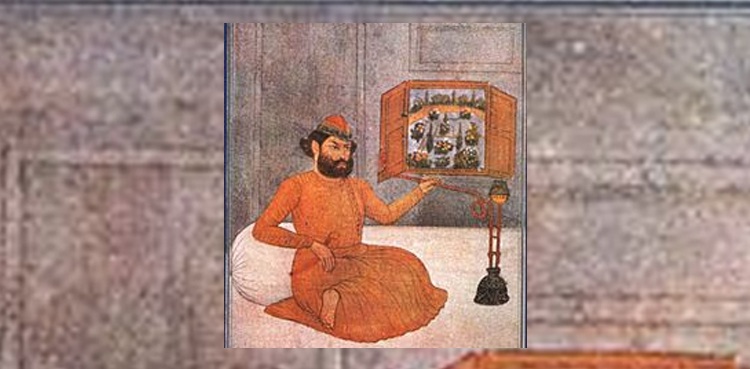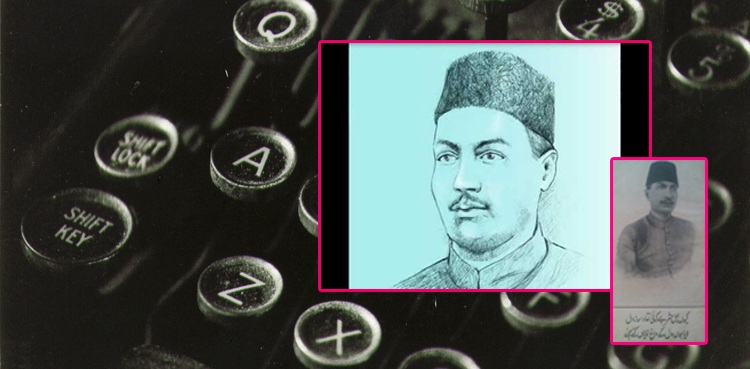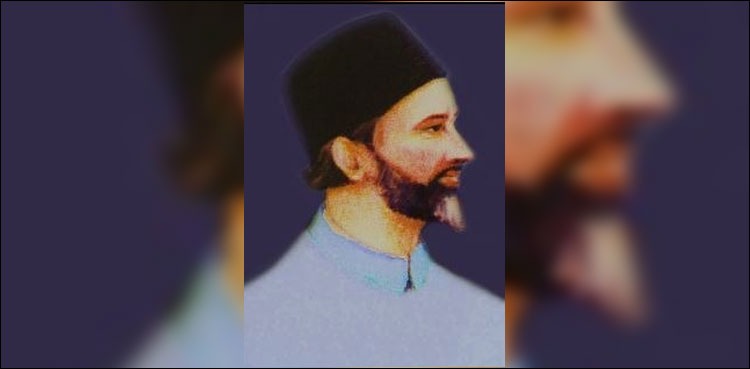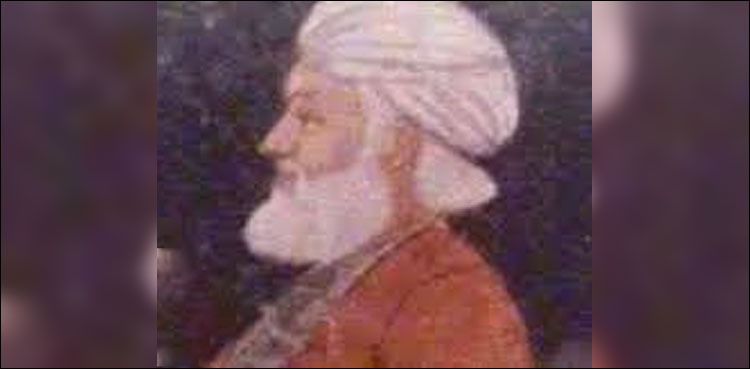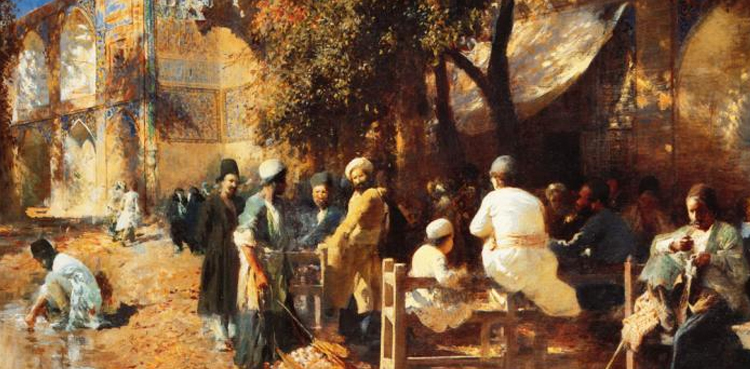ضامن علی نام، جلالؔ تخلص۔ والد کا نام حکیم اصغر علی، خاندانی پیشہ طبابت۔ فارسی کی درسی کتابیں مکمل پڑھیں۔ مزاج میں نزاکت کے ساتھ کچھ چڑچڑا پن۔ پستہ قد، سانولا رنگ، گٹھا ہوا بدن، آواز بلند، پڑھنا بہت بانکا تھا۔ پڑھنے میں کبھی کبھی ہاتھ ہلاتے تھے، اپنا آبائی پیشہ یعنی طبابت بھی نظر انداز نہیں کیا۔
ایک مرتبہ رام پور کے مشاعرہ میں حضرتِ داغؔ دہلوی نے مندرجۂ ذیل مطلع پڑھا:
یہ تری چشمِ فسوں گر میں کمال اچھا ہے
ایک کا حال برا ایک کا حال اچھا ہے
مشاعرہ میں بہت داد دی گئی، مگر جلالؔ مرحوم نے تعریف کرنے میں کمی کی اور جب ان کی باری آئی، ذیل کا شعر پڑھا جس کی بے حد تعریف ہوئی:
دل مرا آنکھ تری دونوں ہیں بیمار مگر
ایک کا حال برا ایک کا حال اچھا ہے
ایک اور مشاعرہ میں جلالؔ نے ایک شعر پڑھا، مولانا عبد الحق مرحوم منطقی خیر آبادی کو وجد آگیا۔ جھوم اٹھے اور بے اختیار آنسو آنکھوں سے جاری ہوگئے:
حشر میں چھپ نہ سکا حسرتِ دیدار کا راز
آنکھ کم بخت سے پہچان گئے تم مجکو
مولانا مرحوم روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ سبحان اللہ کیا با اثر شعر ہے، کس مزے کی بلاغت ہے، رازِ حسرتِ دیدار چھپانے کی انتہائی حد دکھائی ہے، عمر بھر حسرت چھپائی، وقت مرگ بھی افشائے راز نہ ہونے دیا لیکن مقام حشر جو آخری دیدار کی جگہ ہے وہاں حسرتِ دیدار کا راز کسی طرح چھپائے نہ چھپ سکا۔ آنکھ کم بخت سے پہچان گئے تم مجکو۔
(کتاب لکھنؤ کی آخری شمع سے انتخاب)