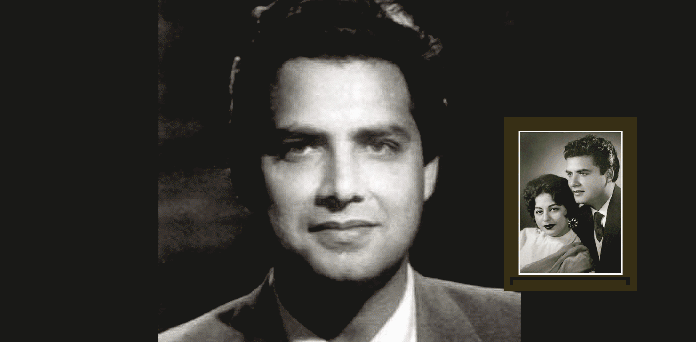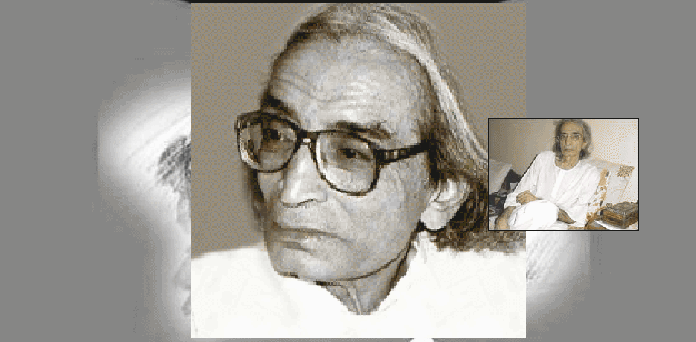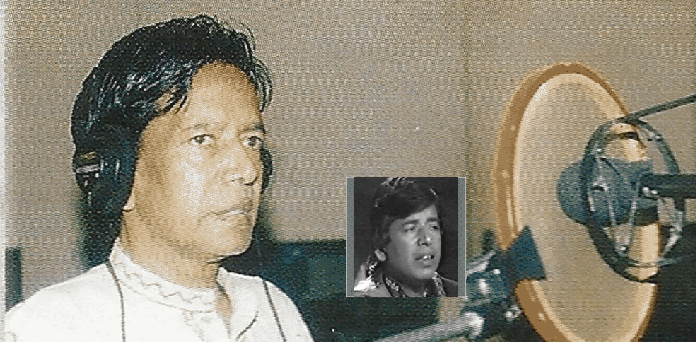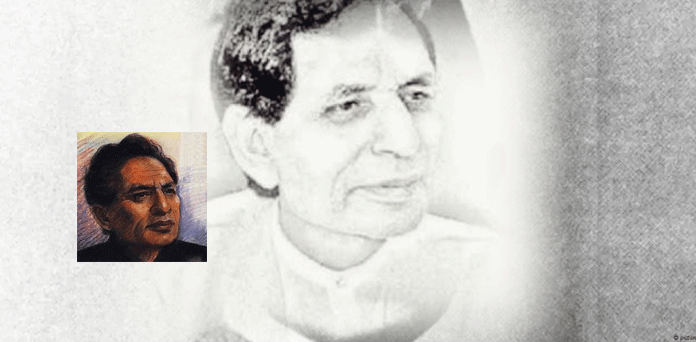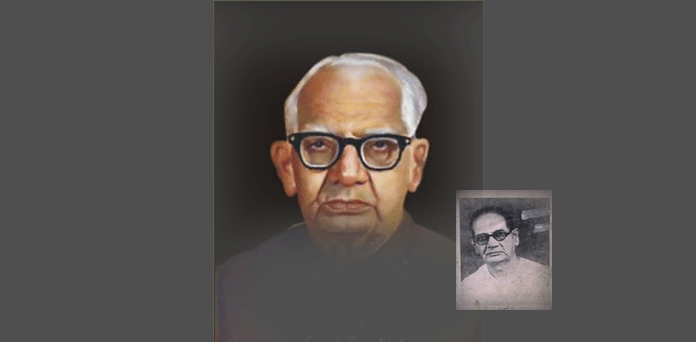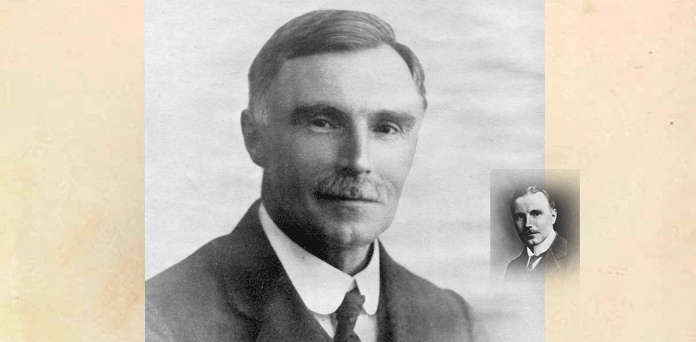یہ تذکرہ ہے آنند نرائن ملّا کا جن کا یہ قول آج بھی بالخصوص بھارت میں اردو کے متوالوں کو مسرور اور اس زبان کو ترک کرنے کا مطالبہ کرنے والوں کو رنجور کیے دیتا ہے کہ ’’میں اپنا مذہب چھوڑ سکتا ہوں، اپنی زبان نہیں چھوڑ سکتا۔ ‘‘
معروف شاعر اور ہندوستان میں اردو کے فروغ کے ایک بڑے حامی آنند نرائن ملّا لگ بھگ صدی جیے۔ وہ 1997ء میں آج ہی کے روز چل بسے تھے۔ جائے پیدائش لکھنؤ اور سنہ پیدائش 1901ء ہے۔ بوقتِ مرگ آنند نرائن ملّا دلّی میں مقیم تھے۔
مسعود حسین خاں لکھتے ہیں، شاعر کے ہاتھ میں شمشیر دے کر اسے ’’مجاہد‘‘ بنا دیتے وقت کوئی بھی اس بارے میں اس کے ردعمل یا جذبات کا لحاظ نہیں رکھتا۔ چنانچہ مجھ سے بھی یہی غلطی ہوتی رہی اور میں پنڈت آنند نرائن ملّاؔ کی اس تقریر کے حوالے سے جو انھوں نے آزادی ملنے کے فوراً بعد جے پور کی اردو کانفرنس میں کی تھی اور کہا تھا۔ ’’میں اپنا مذہب چھوڑ سکتا ہوں، اپنی زبان نہیں چھوڑ سکتا۔‘‘ ان کا قول بارہا اپنی تقریر و تحریر میں نقل کرتا رہا۔ ایک بار تو انجمن ترقی اردو کے ایک تہنیتی جلسے میں، جہاں ملّا صاحب موجود تھے، یہاں تک کہہ گیا: ’’ہے اردو والوں میں کوئی اور مائی کا لال جو اس طرح کا دعویٰ کر سکے؟‘‘
میرے اس مسلسل اصرار پر ملّا صاحب کا ردعمل مجھے حال میں معلوم ہوا جب انھوں نے ایک خط میں لکھا:’’میرے مجاہدِ اردو ہونے کا ذکر تو ہر شخص کرتا ہے لیکن میرے شاعر ہونے کو سب بھول گئے ہیں۔‘‘ مجھے اس ’’شکایت ہائے رنگیں‘‘ سے دھچکا سا لگا۔ یہ نہیں کہ ملّا صاحب کی شاعری کا اعتراف نہیں کیا گیا ہے۔ ان کی سخن وری کا اور ان کے اندازِ بیان کا اعتراف تو بہت پہلے سے ہوتا آیا ہے، یہ اور بات ہے کہ چوں کہ وہ کسی ادبی تحریک کے کفِ سیلاب بن کر نہیں ابھرے اس لیے دوسروں کی طرح ان کا ڈھنڈورا نہیں پیٹا گیا! اس کے ثبوت میں میں آج ۱۹۴۱ء کی ایک دستاویز ’’جدید غزل گو‘‘ کی طرف اشارہ کروں گا، جس کے مرتب اور کوئی نہیں، رسالہ ’’نگار‘‘ کے مستند اور بے پناہ نقاد حضرت نیاز فتح پوری ہیں۔ ’’جدید غزل گو‘‘ میں ۱۹۴۰ء کے آس پاس کے ۳۱ زندہ اور معتبر غزل گوؤں کا انتخابِ کلام یکجا کر دیا ہے۔ یہ انتخاب خود انھیں شاعروں کا کیا ہوا ہے جن کو شامل کیا گیا ہے۔ پنڈت آنند نرائن ملّاؔ کا انتخاب بھی، جو اس وقت ۳۸ برس کے تھے، شامل ہے۔ وہ ایک ایسی بزم کی زینت ہیں جہاں آرزوؔ لکھنوی، ثاقبؔ لکھنوی، جلیل مانک پوری، حسرتؔ موہانی، ساحرؔ دہلوی، سیمابؔ اکبر آبادی، نوحؔ ناروی اور وحشتؔ کلکتوی جیسے جیداساتذۂ سخن براجمان ہیں۔ ۳۱ کی اس فہرست میں صرف احسان دانش اور علی اختر جیسے چند شاعر ان سے جونیئر ہیں۔ ہم عصروں میں خاص نام فراق ؔ گورکھپوری کا ہے۔
انتخاب کے افتتاحیہ نوٹ میں ملّا صاحب نے اپنا سنہ پیدائش اکتوبر ۱۹۰۱ء بتایا ہے۔ ان کی باقاعدہ شعر گوئی کا آغاز ۱۹۲۷ء میں ایک نظم سے ہوا، اس کے ساتھ غزلیں بھی ہونے لگیں۔ جس زمانے کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یعنی ۱۹۴۰ء تک بقول ملّا صاحب ’’پچاس ساٹھ نظمیں اور قریب سو (100) غزلیں کہی تھیں۔ ’’جدید غزل گو‘‘ کے لیے سو شعر انھوں نے انھیں سو غزلوں سے انتخاب کیے ہیں۔ ان سو غزلوں کی بدولت وہ غزل کے آسمانِ شعر میں اتنا بلند مقام حاصل کر چکے تھے کہ نیازؔ اپنی محفلِ سخن کے لیے انھیں دعوت نامہ بھیجنے پر مجبور ہو گئے۔
ملّا صاحب کے احباب کا اصرار تھا کہ انھیں شعر گوئی کے لیے زانوئے تلمّذ کسی استاد کے سامنے تہ کرنا چاہیے کہ یہ دبستانِ لکھنؤ کی روایات کے عین مطابق تھا، لیکن ملّا صاحب یہ جواب دے کر گریز کر گئے: ’’شروع شروع میں میرے احباب نے مجھے مشورہ دیا کہ میں کسی کا شاگرد بن جاؤں، لیکن میرے ذوق نے اسے گوارا نہ کیا۔ اوّل تو یہ کہ شاگردی سے انفرادیت اس قدر مجروح ہوتی ہے کہ وہ پھر جاں بر نہیں ہو سکتی۔ استاد کا رنگ شاگرد کے کلام پر ایک نہ ایک حد تک ضرور حاوی ہو جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ ہر شخص کا تجربہ مختلف ہوتا ہے۔ اس کے جذبات میں مختلف طریقوں سے کیف پیدا ہوتا ہے اور اس کے دل و دماغ پر ایک مخصوص عالم طاری ہوتا ہے جس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا … شاعر کے لیے سب سے پہلے صداقت کی ضرورت ہے اور صداقت دوسرے کے رنگ میں ڈوب کر قائم نہیں رہ سکتی!‘‘۔
آنند نرائن ملّا سے متعلق ادبی مضامین سے اقتباسات میں ان کی شاعری کے آغاز، ان کے فن اور شخصیت ہمارے سامنے آجاتی ہے۔ وہ ہندوستان کے مشترکہ تہذیبی، سماجی اور لسانی کلچر کی زندہ علامت تھے جس کا اظہار اردو سے متعلق ان کے مشہور قول سے ہوتا ہے۔
ملّا کشمیری الاصل تھے لیکن ان کے بزرگ پنڈت کالی داس ملّا لکھنؤ آکر بس گئے تھے اور یہیں پنڈت جگت نرائن ملّا کے یہاں آنند صاحب پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم فرنگی محل لکھنؤ میں ہوئی۔ ان کے استاد برکت اللہ رضا فرنگی محلی تھے۔ اس کے بعد ملا نے انگریزی میں ایم، اے کیا اور قانون کی پڑھائی کی اور وکالت کے پیشے سے وابستہ ہو گئے۔ ۱۹۵۵ میں لکھنؤ ہائی کورٹ کے جج مقرر کئے گئے۔ سبک دوشی کے بعد سیاست کے میدان میں قدم رکھا اور ۱۹۶۷ میں لکھنؤ سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے پارلیمینٹ کے رکن منتخب ہوئے۔ ۱۹۷۲ میں راجیہ سبھا کے رکن بنے۔ آنند نرائن ملّال انجمن ترقی اردو ہند کے صدر بھی رہے۔
ابتداً انھوں نے انگریزی میں شاعری کی اور انگریزی ادب کے طالب علم ہونے کی وجہ سے انگریزی ادبیات پر بہت گہری نظر تھی لیکن پھر اردو شاعری کی طرف آگئے۔ لکھنؤ کے شعری و ادبی ماحول نے ان کی شاعرانہ صفات کو نکھارا۔ جوئے شیر، کچھ ذرے کچھ تارے، میری حدیث عمر گریزاں، کرب آگہی، جادۂ ملّا، ان کے شعری مجموعوں کے نام ہیں۔ کئی ادبی انعامات اور اعزازات سے بھی نوازے گئے۔