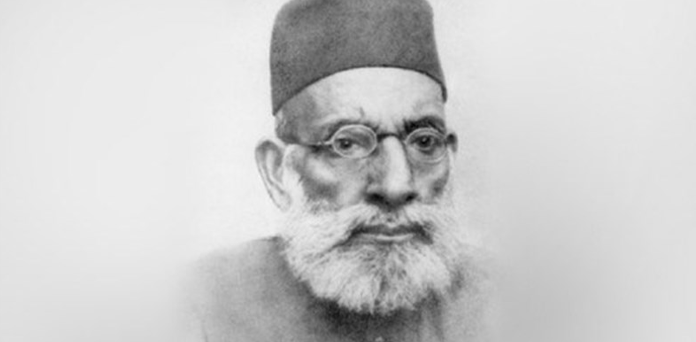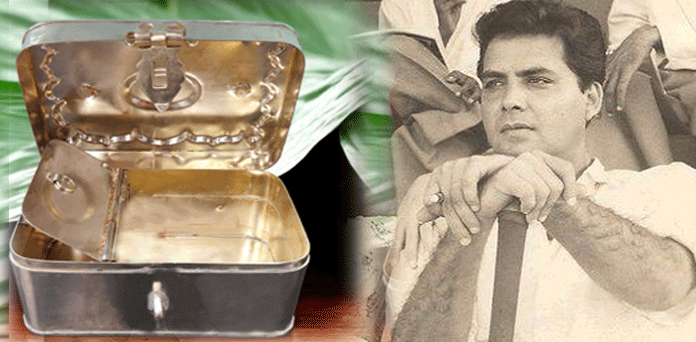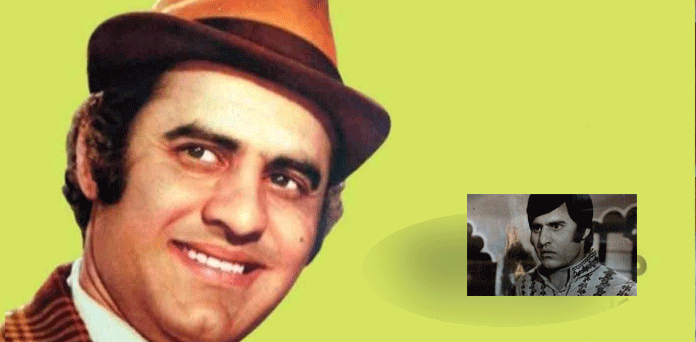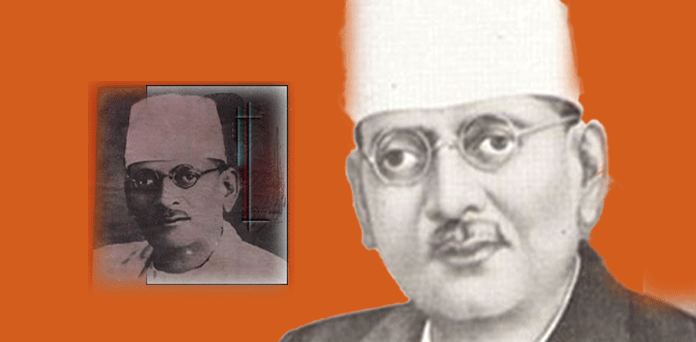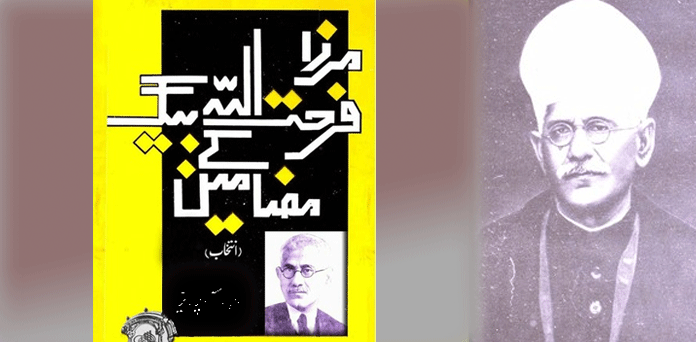دورِ جدید کے غزل گو شعراء میں حسرت کو جو مقام حاصل ہوا، وہ کسی اور کے حصّے میں نہیں آیا۔ حسرت کے کلام میں تغزل کی فراوانی نے انھیں رئیس المتغزلین مشہور کیا۔ وہ ایک جرات مند سیاست داں اور صحافی بھی تھے اور تحریکِ آزادی میں ان کی خدمات اور عملی کاوشیں بھی ناقابلِ فراموش ہیں۔
حسرت کا اصل نام سید فضل الحسن تھا۔ ان کا تخلص حسرت تھا۔ حسرت کا وطن قصبہ موہان ضلع اناؤ تھا۔ 1875ء میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کر کے علی گڑھ گئے اور وہاں سے 1903ء میں بی اے پاس کیا۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد رسالہ اُردوئے معلی نکالا اور باقاعدہ صحافت شروع کی جو ان کے لیے ایک مشن تھا۔ اس رسالہ میں ادبی مضامین کے ساتھ ساتھ سیاسی مضامین بھی ہوتے تھے اور حسرت بھی اپنے افکار کا بے باکانہ اظہار کرتے تھے۔ 1905ء میں انھوں نے آل انڈیا کانفرنس میں حصہ لیا اور اسی وقت سے وہ سودیشی تحریک کے ممبر بن گئے۔ 1907ء میں حسرت کانگریس سے علیحدہ ہوگئے۔ 1908ء میں اُردوئے معلی میں حکومت کے خلاف ایک مضمون چھاپنے کی پاداش میں قید بامشقت کی سزا ہوئی۔ دو سال قید رہنے کے بعد 1910ء میں رہا ہوئے۔ پرچہ دوبارہ جاری کیا لیکن 1904ء میں گورنمنٹ نے پھر بند کر دیا۔ مجبور ہو کر سودیشی مال کا ایک اسٹور قائم کیا۔ اسی زمانے میں جماعت احرار نے جنم لیا۔ مولانا حسرت موہانی اس کے ایک سرگرم کارکن بن گئے۔ اسی نسبت سے رئیس الاحرار بھی کہلائے۔ وہ آزادی کے بہت بڑے داعی تھے اور اپنی سیاسی سرگرمیوں اور قلم کی وجہ سے معتوب رہے۔ 1919ء میں انھیں پھر گرفتاری دینا پڑی۔ ترک موالات کی تحریک میں حصہ لینے کی وجہ سے 1922ء میں تیسری مرتبہ دو سال کے لئے قید ہوگئی۔ 1935ء میں اردوئے معلی پھر جاری کیا۔ 1936ء میں مسلم لیگ کی نظم جدید سے وابستہ ہوگئے۔ تقسیم ہند کے بعد حسرت ہندوستان ہی میں رہے اور وہاں کے مسلمانوں کا سہارا بنے رہے۔ ان کے نظریات عجیب و غریب تھے۔ ایک طرف وہ سوشلزم کے قائل تھے۔ دوسری جانب ان کی زندگی ایک مرد مومن کی زندگی تھی۔ ان کا ظاہر و باطن یکساں تھا ۔ وہ حق بات کہنے میں کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے تھے۔
اُن کی تصانیف میں اپنے کلیات کے علا وہ دیوان غالب کی شرح بے حد مقبول ہوئی۔ مولانا حسرت موہانی کا انتقال 13 مئی 1951ء کو لکھنؤ میں ہوا۔
نقاد اور ماہر لسانیات گوپی چند نارنگ لکھتے ہیں کہ نیاز فتح پوری نے جنوری ۱۹۵۲ء میں سات آٹھ ماہ کے اندر اندر نگار کا ’’حسرت نمبر‘‘ ان کی یاد کے شایان شان شائع کر دیا۔ نیاز نے اس نمبر کے لیے اس زمانے کی تمام بڑی شخصیتوں سے مضامین لکھوائے، مثلاً، مجنوں گورکھپوری، رشید احمد صدیقی، فراق گورکھپوری، آل احمد سرور، احتشام حسین، عبادت بریلوی، کشن پرشاد کول اور خواجہ احمد فاروقی۔ خود نیاز نے اس یادگار نمبر میں پانچ حصے قلم بند کیے اور تذکرۂ حسرت اور انتخاب کلام حسرت کے علاوہ ’’حسرت کی خصوصیات شاعری‘‘ کے عنوان سے جامع مضمون بھی لکھا۔
واقعات جنگِ آزادی ۱۸۵۷ء کے بعد حسرت موہانی اردو شاعروں میں شاید پہلے سیاسی قیدی تھے۔ وہ واقعہ جس پر انھیں قید بامشقت کی سزا ہوئی تھی اب تاریخ کا حصہ ہے۔ ۱۹۰۸ء میں رسالہ اردوئے معلیٰ میں ایک مضمون مصر کے نامور لیڈر مصطفی کمال کی موت پر شائع ہوا جس میں مصر میں انگریزوں کی پالیسی پر بے لاگ تنقید تھی۔ یہ مضمون انگریز سرکار کی نظر میں قابل اعتراض ٹھہرا۔ بقول سید سلیمان ندوی، ’’علی گڑھ کی سلطنت میں بغاوت کا یہ پہلا جرم تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ علی گڑھ کالج کی حرمت کو بچانے کے لیے کالج کے بڑے بڑے ذمہ داروں نے حسرت کے خلاف گواہی دی۔ یہاں تک کہ نواب وقار الملک نے بھی مضمون کی مذمت کی۔ حسرت کو دو برس کی قید سخت کی سزا ہوئی۔ ان کا کتب خانہ اور پریس پولیس کے ظلم وستم کی نذر ہو گیا۔‘‘
اس سانحے کا دلچسپ پہلو جس سے حسرت کے کردار کا اندازہ ہوتا ہے، یہ ہے کہ مضمون حسرت کا نہ تھا۔ مضمون پر کسی کا نام نہیں تھا۔ باوجود اصرار کے حسرت نے اس کے لکھنے والے کا نام نہیں بتایا۔
حسرت کا یہ شعر بہت مشہور ہے
ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی
اک طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی