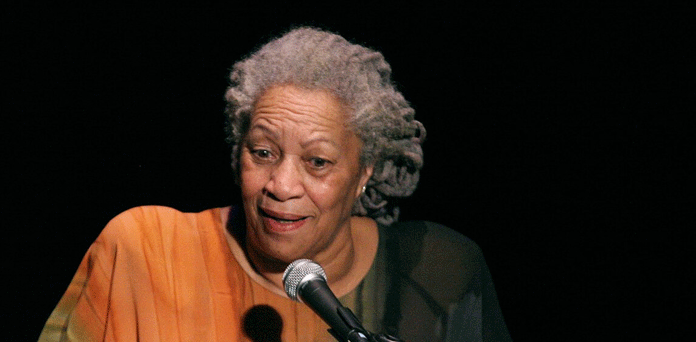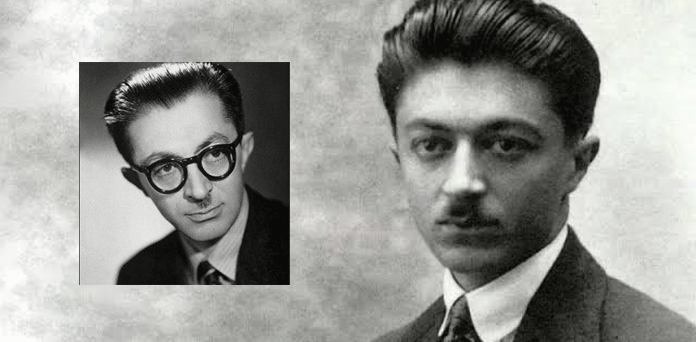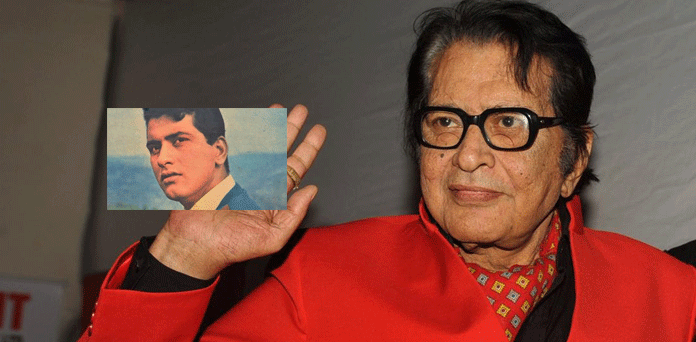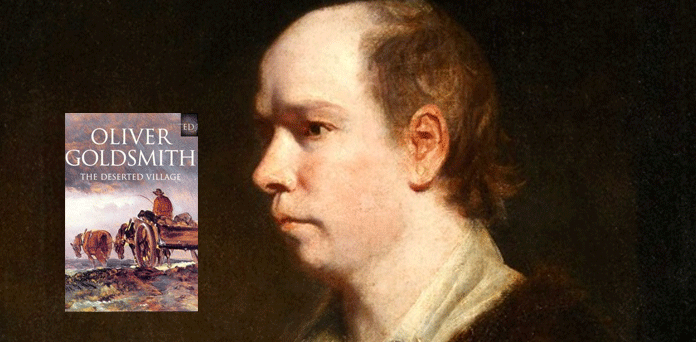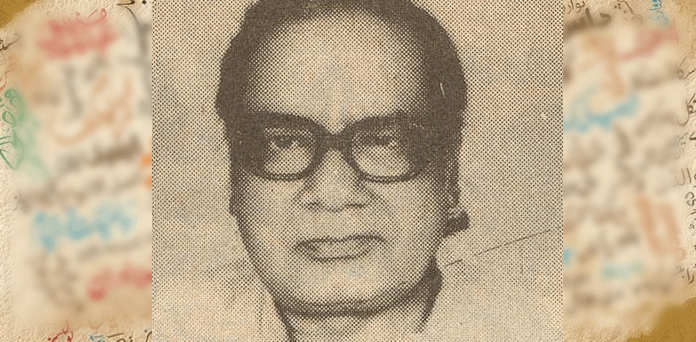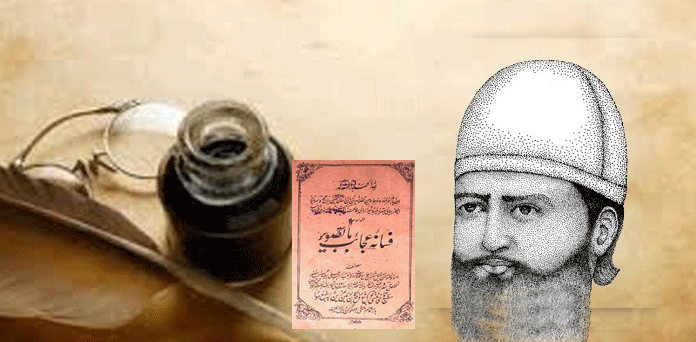اندلس کی امارتِ امویہ کا تذکرہ مسلم تاریخ میں پڑھنے کو ملتا ہے جس کا بانی عبد الرحمن الداخل تھا۔ اسی عبدالرحمن کے بیٹے ہشام نے اپنے باپ کے انتقال کے بعد اس کا جانشیں بنا اور 788ء سے 796ء تک حکمرانی کی۔ محققین کے مطابق ہشام کا انتقال 16 اپریل کو ہوا تھا۔ اسے ہشام اوّل کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔
ہشام اوّل یا ہشام بن عبدالرحمن کے باپ نے 756ء میں خلافتِ عباسیہ کے مقابل امارتِ قرطبہ کو ایک خود مختار امیر کے طور پر سنبھالا تھا۔ عباسیوں کے دمشق پر قبضہ کرنے اور اموی خلافت کو ختم کرنے کے بعد عبدالرحمن اموی خاندان کا زندہ بچ جانے والا ایک شہزادہ تھا۔ بعد میں اس کی حکومت کو اس کے بیٹے ہشام نے آگے بڑھایا۔ ہشام کو اپنے اقتدار کے شروع ہی میں اپنے بھائیوں سلیمان اورعبداللہ کی جانب سے بغاوت کا سامنا کرنا پڑا لیکن وہ ان کو زیر کرنے میں کام یاب ہوگیا۔ ہشام کے بارے میں تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ وہ ایک رحم دل، نرم طبیعت کا مالک، عادل اور فراخ دل حکم ران تھا۔ وہ مذہب کا بھی پابند تھا۔ ابن الاثیر کے الفاظ میں اس کو عمر بن عبدالعزیز جیسا حکم ران کہا جاسکتا ہے۔ مشہور ہے کہ وہ بھی معمولی کپڑے پہن کر قرطبہ کے بازاروں میں گھومتا پھرتا اور عوام کی شکایات سنتا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہشام کی سخاوت کی کوئی حد نہ تھی۔ ہشام ہر مفلس کا مددگار اور ہر مظلوم کا حامی تھا۔ ان سب باتوں کے باوجود اس کا نظم و نسق بہت سخت تھا۔ بغاوتوں کو ہشام نے بڑی سختی سے کچلا اور اس حوالے سے کوئی رعایت نہ کی۔ وہ معمولی جرم کو بھی نظرانداز نہیں کرتا تھا۔
ہشام کے دور میں بعض اہم تعمیراتی کام بھی ہوئے۔ اس نے قرطبہ کی اس جامع مسجد کو مکمل کرایا جسے اس کے والد نے شروع کیا تھا۔ اس نے اپنی مملکت کے شہروں میں بڑی بڑی عمارتیں بنوائیں اور کئی دفاتر تعمیر کیے۔ اس کی حکومت کو 793ء میں مسیحی فرینکس سے خطرہ ہوا تو ہشام نے لشکر کشی کی۔ ہشام ابتدائی بغاوتوں پر قابو پانے کے بعد ایک باغی سردار مطروح بن سلیمان کو سزا دینے کے لیے بڑھا، جس نے فرینک شارلمین کو ہسپانیہ پر حملہ کرنے کے لیے کہا تھا۔ باغی سردار مارا گیا، سارا گوسا اور بارسیلونا ایک مرتبہ پھر اموی حکمران کے زیراثر آ گئے۔ اپنی مملکت میں امن قائم کرنے کے بعد ہشام اس قابل ہو گیا تھا کہ شمالی ہسپانیہ کی طرف توجہ کر سکے، سرحد کے مسیحی قبیلوں نے حملے شروع کر رکھے تھے۔ ان کی سرکوبی ضروری تھی۔ چنانچہ اس نے کئی بغاوتوں کو فرو کرتے ہوئے اپنی فوج کیتبالونیہ سے فرانس میں داخل کی اور دوسرے لشکر نے گلیشیا کے قبائلی لوگوں کو شکست دی۔ ان قبیلوں نے عربوں کے ساتھ صلح کر لی۔
ہشام کے دور میں مالکی فقہ کو رواج دیا گیا۔ وہ امام مالکؒ کا بہت زیادہ احترام کرتا تھا، چنانچہ ہشام کی کوشش سے جزیرہ نما ہسپانیہ میں مالکی فقہ رائج ہو گیا۔ ہشام کا اقتدار آٹھ سال قائم رہا۔ بوقت وفات اس کی عمر صرف 40 برس تھی۔ ہشام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اسلامی قوانین کے نفاذ کی پوری کوشش کی اور خود بھی اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا رہا۔
ہشام کی تدفین قصر قرطبہ کی گئی۔ اسے خدا نے چھے بیٹوں اور پانچ بیٹیوں سے نوازا تھا۔