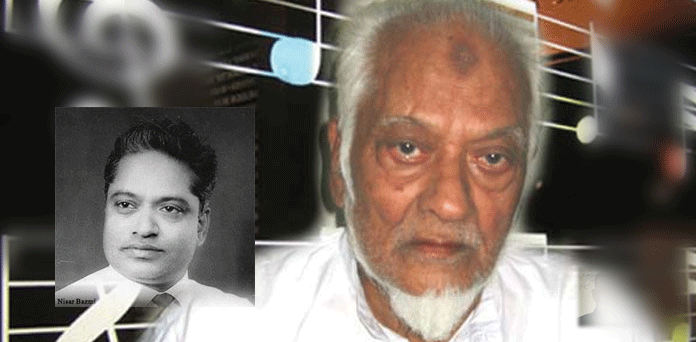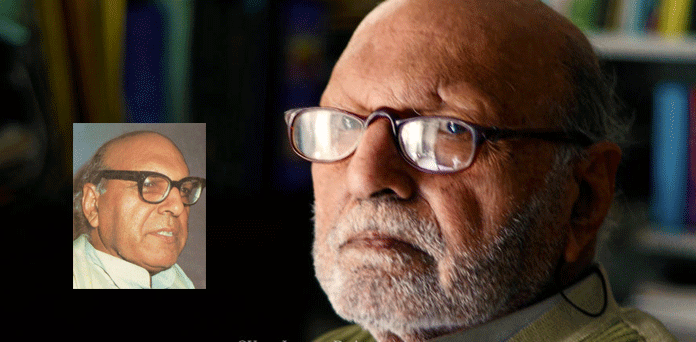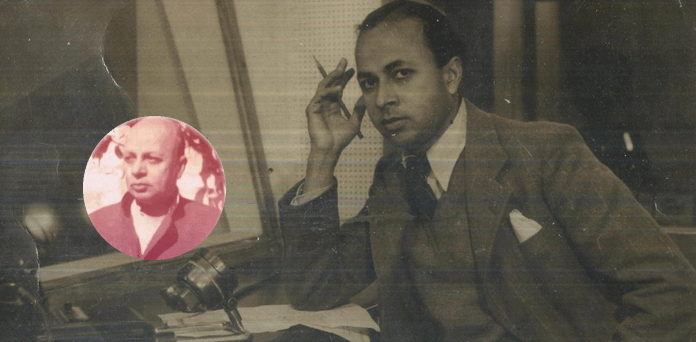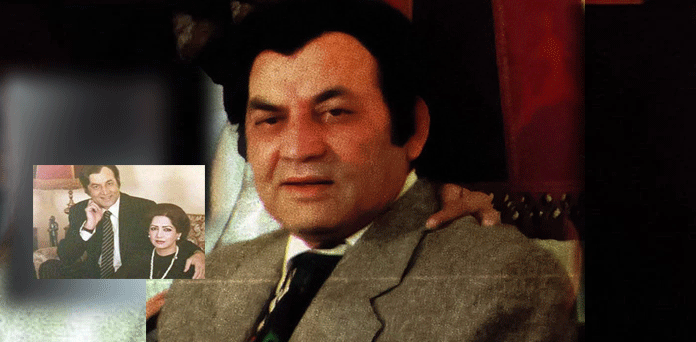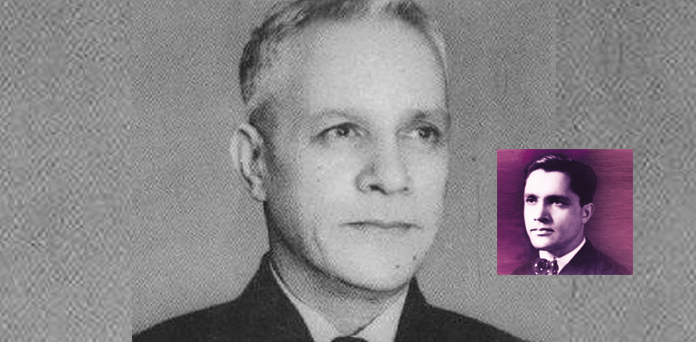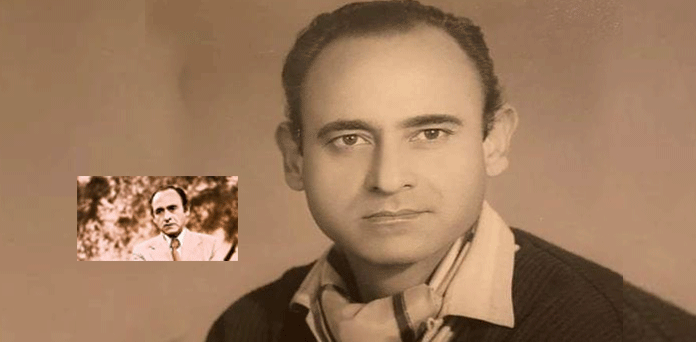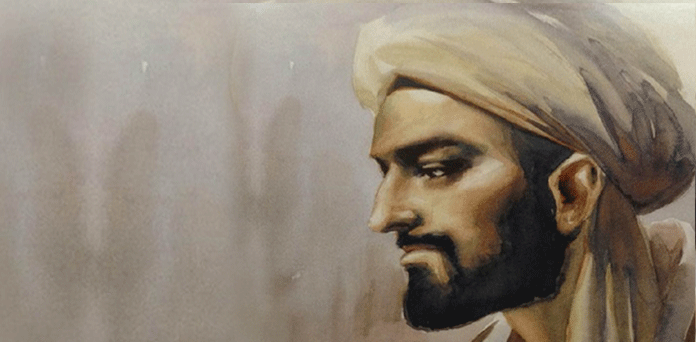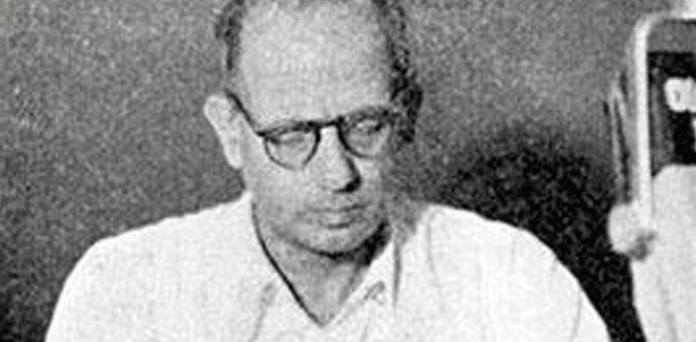اخلاق احمد دہلوی نے اپنی خود نوشت سوانح عمری میں کئی دل چسپ واقعات اور پُرلطف تذکرے رقم کیے ہیں جن کا مطالعہ ہمیں متحدہ ہندوستان کی دلّی، تقسیمِ ہند کے واقعات، مختلف شخصیات اور ریڈیو پاکستان کے اہلِ علم و فن سے آشنائی کا موقع دیتا ہے۔ وہ ایک معروف براڈ کاسٹر ہی نہیں ایک ادیب اور خاکہ نگار بھی تھے۔
اخلاق احمد 12 جنوری 1919ء کو کوچۂ چیلاں، دہلی میں پیدا ہوئے۔ تقسیم ہند کے بعد پاکستان منتقل ہو گئے اور لاہور میں سکونت اختیار کی۔ وہاں وہ ریڈیو پاکستان سے وابستہ رہے اور چند اہم براڈ کاسٹروں میں سے ایک کہلائے۔ ان کے اپنے وقت کے کئی ادیبوں، شعرا اور بڑے بڑے فن کاروں سے دوستی اور یاد اللہ رہی۔ اخلاق احمد نے انہی مشاہیر کے بہت خوب صورت شخصی خاکے تحریر کیے اور ادبی حلقوں میں پہچان بنائی۔ اخلاق احمد دہلوی کے شخصی خاکوں کے تین مجموعے اور بیان اپنا، پھر وہی بیان اپنا اور میرا بیان کے نام سے شایع ہوئے۔ 20 مارچ 1992ء کو اخلاق احمد دہلوی انتقال کرگئے تھے۔ آج ان کی برسی ہے۔ یہاں ہم اخلاق احمد دہلوی کے تذکرے پر مشتمل ایک کالم سے چند پارے نقل کررہے ہیں جو معروف ادیب اور مشہور کالم نگار رفیع الزّماں زبیری نے تحریر کیا تھا۔
اخلاق احمد دہلوی کی خود نوشت سوانح عمری یادوں کا سفر کے نام سے شائع ہوئی تھی۔
زبیری صاحب لکھتے ہیں، دہلی کے مشہور کوچۂ چیلاں میں ان کا بچپن بڑی بڑی شخصیات کے درمیان گزرا۔ مولانا محمد علی جوہر ان کے ہم محلّہ تھے، آصف علی کا مکان ان کے گھر کے بالکل سامنے تھا۔ مولانا محمد علی کے اخبار”کامریڈ” کا دفتر اور پریس بھی تھا۔ اس کے ساتھ جو مسجد تھی وہاں اخلاق احمد قرأت، فارسی اور عربی سیکھتے تھے اور بچوں کو نماز بھی پڑھاتے تھے۔ اخلاق احمد نے نو برس کی عمر میں قرآن شریف حفظ کیا اور رمضان شریف میں دلّی کی جامع مسجد میں محراب سنائی۔ اس تقریب میں مولانا محمد علی، شوکت علی، مولانا احمد سعید، مفتی اعظم کفایت اللہ اور حسن نظامی جیسے بزرگوں نے شرکت کی۔ وہ بتاتے ہیں کہ غدر کے زمانے سے آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کی پوتی شہزادی ہمارے ہاں مقیم تھیں۔ ان کا میں لے پالک تھا اور ان بزرگ خاتون کی وجہ سے ہمارے گھر میں ان نامور شخصیات کا مجمع لگا رہتا تھا۔
اخلاق احمد جب چوتھی پانچویں جماعت میں تھے تو انھیں شعر کہنے کا شوق پیدا ہوا۔ یہ ایک مشاعرے میں گئے اور وہاں اپنی زندگی کی پہلی اور آخری غزل پڑھی جس کا ایک شعر یہ تھا۔
شمع سے پوچھے کوئی کیوں اشک بار ہے
پروانہ اس کے حسن پہ جب خود نثار ہے
تابش دہلوی اور شان الحق حقی دونوں شاعر اخلاق احمد کے اسکول کے ساتھی تھے۔ ان سے یہ ضرور متاثر ہوئے۔ دہلی کے کوچہ چیلاں میں بھی کچھ ایسی ہستیاں تھیں جن کا اخلاق احمد نے اپنی کتاب میں زور و شور سے ذکر کیا ہے۔ یہ سب ان کے بچپن کے دورکی یادیں ہیں۔ اخلاق احمد نے جب میٹرک پاس کرلیا تو اب یہ فیصلہ ہونا تھا کہ وہ آگے کیا کریں گے۔ ان کی والدہ مرحومہ نے ان کی تعلیم و تربیت کی ذمے داری اپنی پھوپھی زاد بہن بیگم نور الحسن برلاس کو سونپی تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ یہ علی گڑھ کالج جاکر پڑھیں۔ ان کی دادی انھیں دینی علوم کی تعلیم کے لیے دیوبند بھیجنا چاہتی تھیں۔ اسی کشمکش کے دوران خواجہ حسن نظامی نے انھیں اپنے ہفتہ وار اخبار ”ڈکٹیٹر” میں نائب ایڈیٹر بنا دیا مگر یہ رسالہ ایک بار چھپ کر بند ہوگیا۔ آصف علی نے یہ دیکھا تو انھیں بلاکر مولوی عبدالحق کے پاس بھیج دیا کہ جاؤ ان کے پاس انجمن ترقی اردو میں کام کرو جب تک آیندہ تعلیم کے بارے میں فیصلہ ہو۔ وہاں کیا ہوا، یہ اخلاق احمد سے سنیے۔ لکھتے ہیں ”مولوی صاحب نے پوچھا، آپ نے کچھ پڑھا لکھا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ اردو پڑھی ہے۔ فرمایا، اردو میں کیا پڑھا ہے؟ میں نے کہا، جتنی کتابیں اردو میں اب تک چھپ چکی ہیں۔ مولوی صاحب کی تیوری چڑھ گئی۔ کہنے لگے، جائیے۔ آصف علی صاحب سے میرا سلام کہیے اور کہیے مجھے اتنا پڑھا لکھا آدمی نہیں چاہیے۔”
اخلاق احمد نے جب یہ ساری روداد آصف علی کو سنائی تو انھوں نے ڈانٹا اور کہا کہ حصولِ علم اپنی جہالت کی آگاہی کے لیے ہوتا ہے، شیخی بگھارنے کے لیے نہیں۔ پھر انھوں نے دوبارہ مولوی صاحب سے سفارش کی، اخلاق احمد نے بھی اظہار شرمندگی کیا تو مولوی صاحب نے مولوی احتشام الحق حقی کے زیرِ نگرانی اردو لغت کے کام پر ان کا تقرر کر دیا۔
اخلاق احمد لکھتے ہیں۔ ”1941 میں میری عمر اکیس برس کی ہوگئی، اگر میٹرک کا امتحان پاس کر لینے کے بعد میری تعلیم کا سلسلہ جاری رہتا تو مجھے اب بی اے کر لینا چاہیے تھا لیکن میں میٹرک کرتے ہی خواجہ حسن نظامی کے ہفت روزہ اخبار کا ایڈیٹر بن کر باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے سے ایک طرح سے محروم ہوگیا، پھر مولوی احتشام الحق حقی کے ساتھ اردو لغت کی ترتیب کے کام میں لگ گیا ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بقول احمد شاہ بخاری کے پڑھے نہ لکھے نام محمد ترقی پسند۔”
لغت کا کام حقی صاحب کا انتقال ہوجانے پر ختم ہوگیا تو اخلاق احمد کو ملٹری اکاؤنٹس میں ملازمت مل گئی، پہلی پوسٹنگ میرٹھ میں ہوئی۔ کلرکی ان کے بس کی نہ تھی، چھ مہینے میں واپس دلّی آگئے۔ بیرسٹر آصف علی کے وسیلے سے آل انڈیا ریڈیو دلّی میں اناؤنسر کی جگہ مل گئی۔ یہاں بھی یہ لطیفہ ہوا کہ جس دن یہ اناؤنسر بنے اسی دن سے اناؤنسر سرکاری ملازم نہ رہے، کنٹریکٹ پر اسٹاف آرٹسٹ بن گئے، یعنی پنشن اور دوسری سرکاری مراعات سے محروم ہو گئے۔
میرٹھ میں اگرچہ ان کا قیام مختصر تھا مگر وہاں کی باتیں دلچسپ ہیں۔ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔
اخلاق احمد نے جب ریڈیو میں کام شروع کیا توکرشن چندر نے جو وہاں پہلے سے تھے، چاہا کہ اخلاق احمد ریڈیو مسودہ نگار بنیں۔ ان سے انھوں نے ایک مسودہ بھی لکھوایا لیکن ن۔ م۔ راشد اور حفیظ جاوید کا اصرار تھا کہ اخلاق احمد کو اناؤنسر رہنا چاہیے، آغا اشرف استعفیٰ دے کر جاچکے تھے، دوسرے اناؤنسر الیاس کا انتقال ہوگیا، غلام محی الدین بھی چلے گئے۔ اب تین مشہور ڈرامہ آرٹسٹ شکیل احمد، راج نارائن مہرا اور برہما نند متل دلّی ریڈیو اسٹیشن پر اناؤنسر بنا دیے گئے تھے۔ کچھ عرصے بعد اخلاق احمد ریڈیو پر خطوط کا جواب بھی دینے لگے۔ دلّی ریڈیو اسٹیشن پر ان دنوں ادیبوں کا جمگھٹا تھا۔ اخلاق احمد نے اس دورکی یادوں کو خوب تحریرکیا ہے۔ میرا جی، منٹو، اختر الایمان اور دوسرے ساتھیوں کا ذکر کیا ہے، یہ دلچسپ تحریریں ہیں۔
پھر جب آزادی کی تحریک اور کانگریس اور مسلم لیگ کے اختلافات نے زور پکڑا تو اس کے اثرات ہر طرف نمایاں ہونے لگے۔ اخلاق احمد لکھتے ہیں۔ 1945-46 کا زمانہ خاصا افراتفری کا تھا۔ ہندو مسلم فسادات کا عہد۔ ہر طرف شور شرابا، مار کٹائی، گویا سارے ملک کی اینٹ سے اینٹ بج رہی تھی اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالی جا رہی تھی۔ سردار پٹیل جب انفارمیشن اور براڈ کاسٹنگ کے وزیر مقرر ہوئے تو ریڈیو کے مسلمان ملازمین کے لیے حالات خراب ہونے شروع ہوگئے۔ احمد شاہ بخاری کو یہ کہہ کر سبکدوش کردیا گیا کہ ریڈیو بخاری کے بغیر بھی چل سکتا ہے۔ آخر وہ دن آیا کہ دن گنے جاتے تھے جس دن کے لیے 3 جون 1947 کو پاکستان بننے کا اعلان کر دیا گیا۔
اخلاق احمد لکھتے ہیں ”3 جون کی یہ شام اس برصغیر میں کوئی بھلا ہی نہیں سکتا۔ ایسی تاریخ ساز شام جس میں پاکستان بننے کا اعلان ہوا اور ہندوستان کی آزادی کی تاریخ مقرر ہوئی۔ میں نے ریڈیو کی اپنی 39 سالہ زندگی میں کوئی ایسی رنگین شام نہیں دیکھی جس میں مہمان خصوصی تھے لارڈ ماؤنٹ بیٹن، قائداعظم محمد علی جناح، جواہر لال نہرو اور سردار بلدیو سنگھ اور میزبان عمومی تھے۔ یعنی سید انصار ناصری، مسعود الحسن تابش، آغا صفدر، بی این متل کلارک اور میں۔”
اخلاق احمد دہلوی اپنے قافلے کے ہمراہ 10 فروری 48ء کو پاکستان پہنچے۔ لکھتے ہیں ”میں لاہور پہنچتے ہی فکر معاش میں اچھرے سے شملہ پہاڑی پیدل پہنچا۔ جیسے ہی ریڈیو اسٹیشن میں داخل ہوا تو یوں محسوس ہوا جیسے نئے سرے سے ماں کے پیٹ میں آگیا ہوں۔ سب کے سب اس تپاک سے ملے، گویا ایک زبان ہوکر کہہ رہے ہوں۔
بہت دیر کی مہرباں آتے آتے