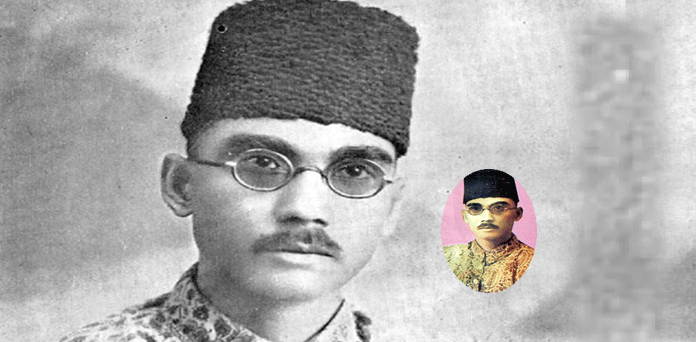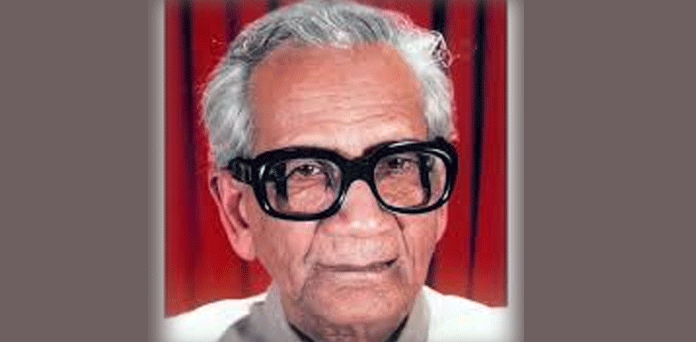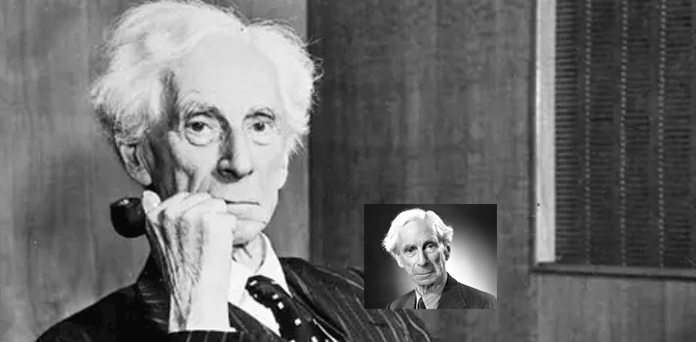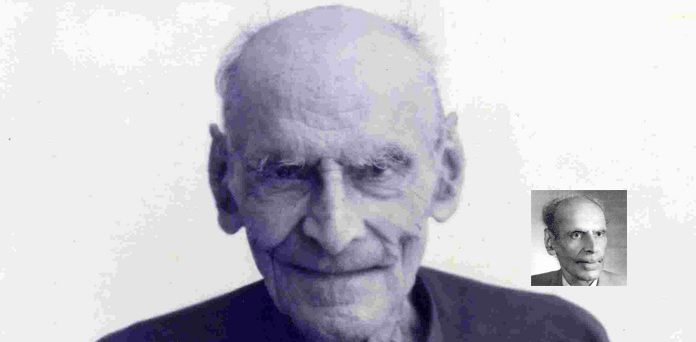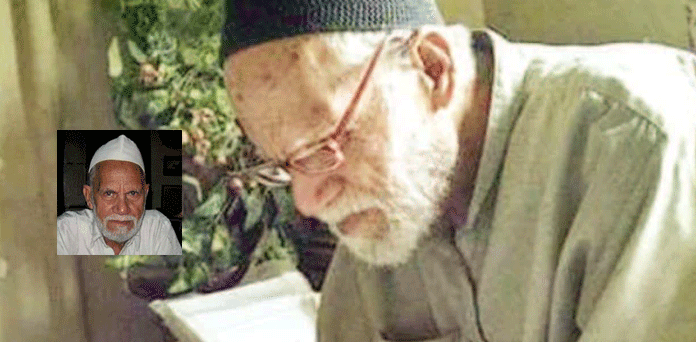2022ء میں آج ہی کے روز گلوکارہ لتا منگیشکر اس دنیا سے رخصت ہوگئی تھیں۔ ان سے بہت پہلے ہندوستان کے مشہور غزل گائیک جگجیت سنگھ قیدِ حیات سے رہائی پاچکے تھے جنھوں نے ایک موقع پر لتا منگیشکر کو ان الفاظ میں خراجِ تحسین پیش کیا تھا، ’20 ویں صدی کی تین چیزیں یاد رکھی جائیں گی۔ ایک انسان کا چاند پر جانا، دوم دیوارِ برلن کا گرنا اور تیسرا لتا منگیشکر کا پیدا ہونا۔‘
دیکھا جائے تو فنِ موسیقی کی باریکیوں کو سمجھنے والوں کے لیے بھی شاید یہ بہت مشکل رہا ہو کہ لتا جی کو کیسے سراہا جائے، ان کی تعریف میں کیا کہیں یا وہ کیا الفاظ ہوں جن کا سہارا لے کر لتا جی کے فن کی عظمت کو بیان بھی کرسکیں اور اس گلوکارہ کے شایانِ شان بھی ہوں۔ لیکن پھر سب نے بڑی سہولت اور رعایت سے انھیں لتا جی اور دیدی کہہ کر پکارنا شروع کردیا اور یہی ان سے عقیدت اور پیار کا بہترین اظہار ثابت ہوا۔ لتا منگیشکر 92 برس زندہ رہیں اور لگ بھگ 60 برس تک سُر، تال، ساز و آواز کی دنیا میں مشغول رہیں۔
ہیما منگیشکر المعروف لتا منگیشکر کو لافانی گائیک بنانے کا سہرا میوزک ڈائریکٹر ماسٹر غلام حیدر کے سر ہے جن کا تعلق لاہور کے علاقہ چونا منڈی سے تھا۔ لتا منگیشکر نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ ’یہ سنہ 1947 کا زمانہ تھا اور فلم ‘شہید’ کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ اس زمانے کے نام ور میوزک ڈائریکٹر ماسٹر غلام حیدر نے مذکورہ فلم کے ایک گیت کے لیے میرا آڈیشن لیا۔‘ وہ بتاتی ہیں ’ماسٹر صاحب کو میری آواز بہت پسند آئی اور میرے کہے بغیر انھوں نے اپنے من میں یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ مجھے پروموٹ کریں گے، انھی دنوں کی بات ہے کہ فلمستان اسٹوڈیو کے مالک اور مشہور پروڈیوسر شیشدھرمکھر جی نے ریہرسل میں میری آواز سُنی اور مجھے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ ’اس لڑکی کی آواز بہت باریک اور چبھتی ہوئی ہے۔‘ شیشدھر مکھر جی اپنے وقت کے بہت بڑے فلم ساز تھے۔ لتا منگیشکر کے مطابق ’ماسٹر غلام حیدر نے شیشدھر مکھر جی سے کہا کہ یہ لڑکی (لتا) برصغیر کی میوزک مارکیٹ میں اچھا اضافہ ثابت ہوں گی لیکن وہ نہ مانے۔‘ ’شیشدھر کے انکار پر ماسٹر غلام حیدر ناراض ہو گئے اور کہا ’مکھرجی صاحب ویسے تو آپ کو اپنی رائے قائم کرنے کا پورا حق ہے لیکن میرے الفاظ نوٹ کر لیں ایک دن آئے گا کہ پروڈیوسر، لتا کے دروازے پر قطار باندھے کھڑے ہوں گے۔‘ ان کی یہ پیش گوئی درست ثابت ہوئی۔
لتا منگیشکر 28 ستمبر 1929ء کو متحدہ ہندوستان کے شہر اندور میں پیدا ہوئی تھیں۔ ان کے والد دِینا ناتھ منگیشکر گلوکار اور اداکار تھے۔ لتا منگیشکر بھی شروع سے ہی گلوکاری کی طرف مائل ہوگئیں۔ کمال امروہوی کی فلم ’’محل‘‘ 1949 میں ریلیز ہوئی تھی جس کا گانا’’آئے گا ،آئے گا ،آئے گا آنے والا، آئے گا‘‘ لتا منگیشکر نے گایا تھا اور یہ گانا مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچا۔ اس گیت کو آج بھی اسی ذوق و شوق سے سنا جاتا ہے۔ اس کے بول کچھ یوں ہیں’’خاموش ہے زمانہ چپ چاپ ہیں ستارے…آرام سے ہے دنیا بے کل ہیں دل کے مارے… ایسے میں کوئی آہٹ اس طرح آ رہی ہے…جیسے کہ چل رہا ہے من میں کوئی ہمارے …یا دل دھڑک رہا ہے اِک آس کے سہارے …آئے گا آئے گا آئے گا آنے والا آئے گا…۔‘‘ یہ نخشب جارچوی کا تحریر کردہ خوب صورت گیت تھا جس کی موسیقی کھیم چند پرکاش نے ترتیب دی تھی۔ اس گانے نے لتا منگیشکر پر فلم انڈسٹری کے دروازے کھول دیے۔ فلم کے ہیرو اور فلم ساز بھی اداکار اشوک کمار تھے اور ان کی ہیروئن مدھو بالا تھیں۔ فلم کے مصنف اور ہدایت کار کمال امروہوی تھے۔
اس گیت کی ریکارڈنگ کا بھی دل چسپ قصہ ہے۔ مشہور ہے کہ جب یہ گیت ریکارڈ کیا گیا تو ’آئے گا، آئے گا‘ کا تأثر گہرا کرنے اور اسے حقیقت کا رنگ دینے کے لیے لتا جی نے چل پھر کر اسے ریکارڈ کرایا۔ یوں دھیمے سروں سے گیت آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لتا جی کی آواز خوشبو بن کر پھیلی اور برصغیر میں ان کا خوب شہرہ ہوا۔
لتا منگیشکر نے اپنے کریئر کا آغاز 1942 میں کیا۔ تاہم انھوں نے اردو فلموں کے لیے پہلا گانا 1946 میں ‘آپ کی سیوا’ نامی فلم کے لیے گایا۔ بولی وڈ میں ان کی شہرت کا آغاز 1948 میں فلم ‘مجبور’ کے گیت دل میرا توڑا سے ہوا اور اگلے سال فلم ‘محل’ سامنے آئی جس کے بعد لتا نے مڑ کر نہیں دیکھا۔
لتا منگیشکر کا نام 1974 سے 1991 تک سب سے زیادہ گانوں کی ریکارڈنگ کے حوالے سے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل رہا۔ یہ نام 2011 تک ورلڈ ریکارڈ کا حصہ رہا۔ دینا ناتھ کی بیٹیوں میں نہ صرف لتا نے بلکہ ان کی بہن آشا بھوسلے نے بھی گلوکارہ کے طور پر اہم مقام حاصل کیا۔
گلوکارہ لتا منگیشکر کے گیتوں کا ترنم، نغمگی اور تازگی گویا سماعت پر ایک سحر سا طاری کر دیتی ہے اور ان کے گائے ہوئے گیت دل ميں اُتر جاتے ہیں۔ سُروں کی ملکہ لتا منگیشکر کورونا وائرس کا شکار ہونے کے بعد طبّی پیچیدگیوں کے سبب زندگی کی بازی ہار گئی تھیں۔