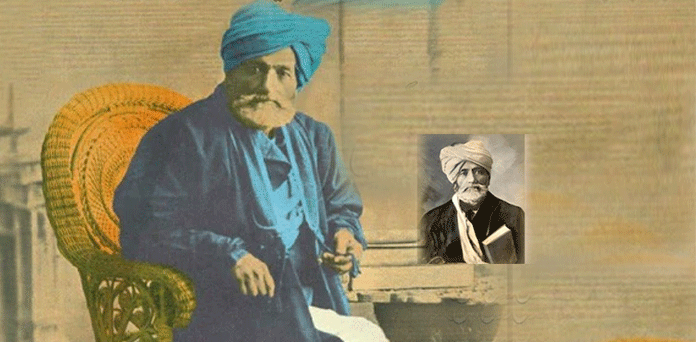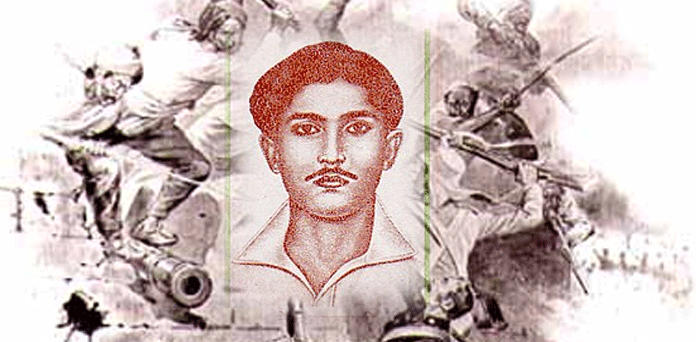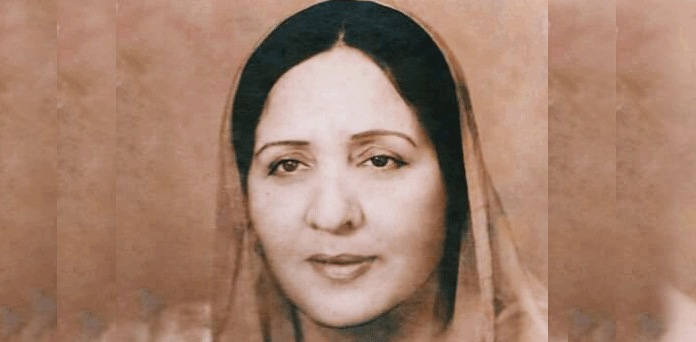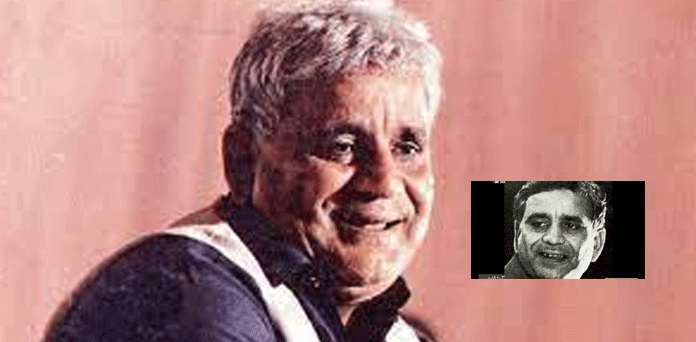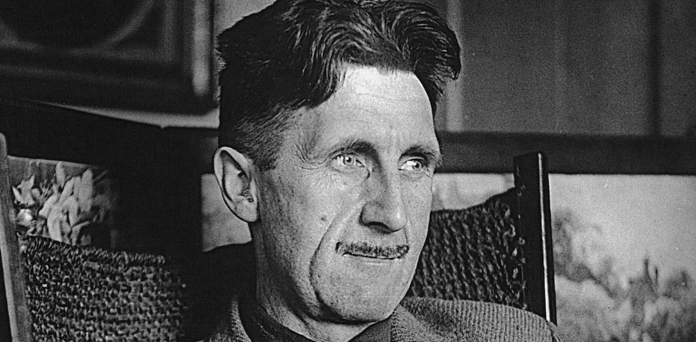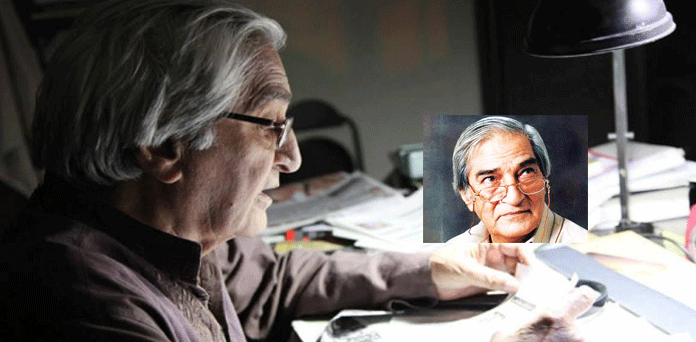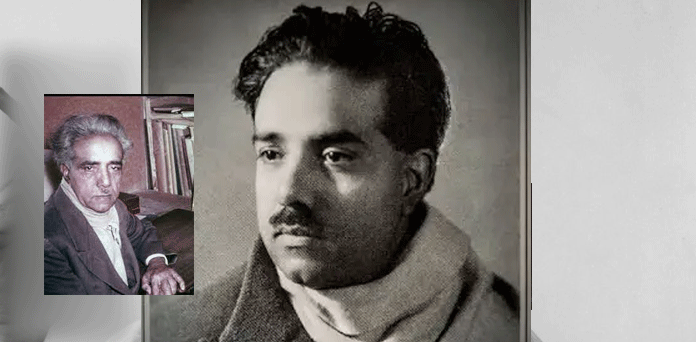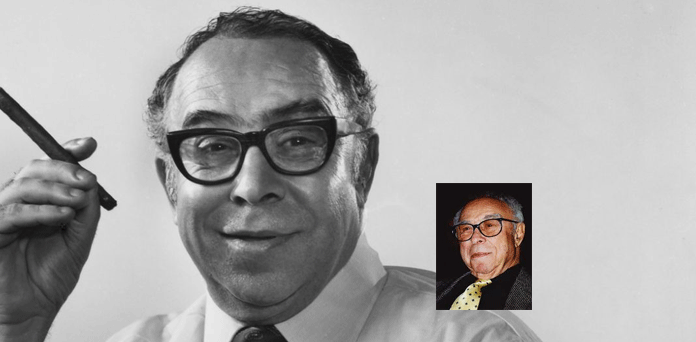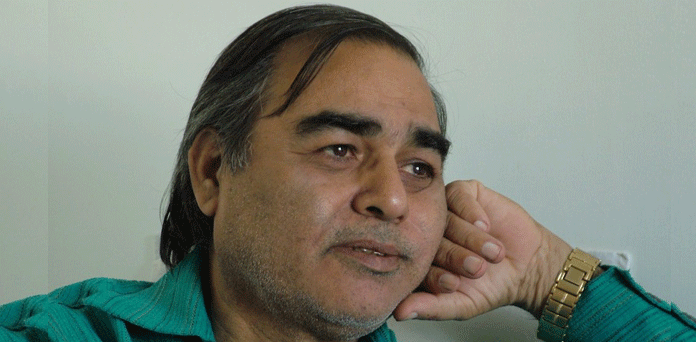کیسے کیسے گوہرِ نایاب مٹی ہوگئے اور کیا نابغۂ روزگار شخصیات تھیں جو رزقِ خاک ہوئیں۔ وہ ادیب و شاعر جن کے فن کی عظمت کا تذکرہ اور قلم کی رفعت کا شہرہ کبھی ہر طرف ہوتا تھا، آج بتدریج ان کا نام ذہن سے اترتا جاتا ہے۔ یہ تذکرہ اردو کے صاحبِ طرز انشاء پرداز، بلند پایہ ادیب اور شاعر محمد حسین آزادؔ کا ہے جن کا آج یومِ وفات ہے۔ جب بھی اردو ادب کی تاریخ، اور اہلِ قلم کے فن و اسلوب کو موضوع بنایا جائے گا، اپنے زمانے کے اس بے مثل ادیب کا تذکرہ ضرور کیا جائے گا۔
بلند پایہ اور صاحبِ طرز انشا پرداز، ناقد، محقق، شاعر اور صحافی محمد حسین آزادؔ کے فن اور ان کی شخصیت پر بات کرنے کو دفتر درکار ہے۔ ان کی ادبی تخلیقات اور اور زبان و ادب کے لیے خدمات کے کئی پہلو اور بہت سے گوشے تشنۂ تحقیق ہیں۔ جدید نثر کے معمار اور جدید نظم کی داغ بیل ڈالنے والے آزاد نے نیرنگِ خیال جیسی تصنیف کی شکل میں اردو تنقید کو نقشِ اوّل عطا کیا۔ اپنے منفرد و بے مثل اسلوب کے ساتھ آزاد نے اس کتاب میں قدیم تذکروں کے مروجہ انداز سے انحراف کیا ہے۔ اسے نثر کا اعلیٰ نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ آگے ہم آبِ حیات و دیگر کتابوں کا تذکرہ کریں گے، لیکن پہلے ان کے حالاتِ زیست پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
محمد حسین آزاد جنگ آزادی میں بغاوت کے بعد شہادت پانے والے پہلے ہندوستانی صحافی مولوی محمد باقر کے اکلوتے فرزند تھے۔ مولوی باقر اردو کے پہلے اخبار ‘دہلی اردو اخبار’ کے مالک اور ایڈیٹر تھے اور انگریز سامراج کے خلاف مضامین لکھتے اور شایع کرتے تھے۔ 1857 میں جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد جھوٹے الزام میں مولوی باقر کو گرفتار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ محمد باقر تھا ظاہر ہے علمی و ادبی شخصیت تھے استاد ذوق کے دوست تھے۔ اور یوں آزادؔ کو ابتدائی تعلیم و تربیت کے لیے ذوق جیسے شاعر کی صحبت کے سایٔہ عاطفت نصیب ہوا۔ انہی سے موصوف نے شعر گوئی اور فنِ عروض سیکھا۔ عربی اور فارسی اپنے والد سے سیکھی تھی اور بعد میں دہلی کالج میں داخلہ لیا۔ شاعری کا شوق تو بچپن ہی میں ہوگیا تھا اور ذوقؔ کے ساتھ بڑے بڑے مشاعروں میں جاتے جہاں استاد شعراء کو سنتے تھے۔ والد کی شہادت کے بعد انھیں گھر بار چھوڑنا اور دہلی سے لکھنؤ فرار ہونا پڑا۔ املاک ضبط کر لی گئی۔ اور لکھنؤ میں رشتے داروں کے پاس رہنا پڑا۔ 1864ء میں ٹھوکریں کھانے کے بعد تلاش روزگار میں لاہور کا رخ کیا۔ ایک پوسٹ آفس میں عارضی ملازمت بھی کی۔ محکمہ تعلیم میں نوکری بھی کی اور انگریزوں کو اردو بھی پڑھائی۔ برطانوی دور کی حکومتِ پنجاب نے ان سے اردو کی درسی نصابی کتابیں بھی لکھوائیں۔ آزاد پر جب قسمت مہربان ہوئی تو گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی فارسی پڑھانے کی ذمہ داری مل گئی۔ معاشی حالات بہتر ہوئے تو آزاد کی ادبی تخلیقی صلاحیتوں کو ابھرنے کا موقع ملا اور حالی کے ساتھ آزاد کا بھی جدید نظم کے موجدوں میں شمار ہوا۔ انھوں نے ایران، بخارا اور کابل کا سفر بھی کیا۔
آزادؔ کو ان کے تعلیمی و تصنیفی اور سرکاری کارناموں کی وجہ سے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ آغا محمد باقر لکھتے ہیں کہ: ‘‘۱۸۸۷ء میں مولانا آزاد ؔ کو ملکہ وکٹوریا کی جوبلی کے موقعہ پرتعلیمی اور ادبی خدمات کے صلے میں شمس العلماء کا خطاب ملا۔’’
اردو ادب کو اپنی تخلیقات سے مالا مال کرنے والے محمد حسین آزاد کی شاہ کار اور یادگار تصانیف کا مختصر تعارف باذوق قارئین خاص طور پر ادب کے طلبہ کی دل چسپی کا باعث بنے گا۔
آغاز کرتے ہیں قصصِ ہند سے جو تین حصّوں پر مشتمل ہے۔ اس تصنیف میں پہلا حصہ ماسٹر پیارے لال آشوب کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اس کا تیسرا حصہ کرنل ہالرائیڈ کے ایما پر سر رشتۂ تعلیم پنجاب کے اراکین نے ترتیب دیا اور قصصِ ہند کا دوسرا حصہ محمد حسین آزادؔ کا پہلا ادبی اور علمی کارنامہ ہے۔ اس کے بعد ایک عرصہ تک آزادؔ نے کسی مستقل تصنیف کی طرف توجہ نہیں کی۔ عتیق اﷲ لکھتے ہیں کہ: ’’قصصِ ہند میں کسی خاص عہد یا ہندوستان کی مکمل و مبسوط تاریخ کو موضوع نہیں بنایا گیا ہے بلکہ محض ان چیدہ چیدہ تاریخی شخصیات ہی پر خاص توجہ کی گئی ہے۔ جو مختلف وجہ سے توجہ طلب رہی ہیں۔آزاد نے انہیں بڑی بے تکلف اور حکائی زبان میں اد اکرنے کی سعی کی ہے۔ آزاد نے بڑی حد تک معروضیت کا بھی خیال رکھا ہے ۔ ‘‘
قصصِ ہند میں محمود غزنوی، شہاب الدین غوری، علاء الدّین، ہمایوں، اکبر، نور جہاں، شاہ جہاں، اورنگ زیب، شیوا جی وغیرہ وغیرہ کے کچھ حالات و واقعات کا ذکر ہے۔ اس میں آزاد نے ہندوستان کے کچھ مشہور قصوں کہانیوں کو عام فہم زبان میں بیان کیا ہے۔
اب چلتے ہیں آبِ حیات کی طرف جسے مولانا محمد حسین آزادؔ کی شاہکار اور بہترین تصنیف شمار کیا گیا۔ اس میں مشہور شعراء کے حالات مع نمونۂ کلام اور مصنّف دل چسپ انداز میں تنقید کی جھلک دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس سے قبل اس قسم کا تذکرہ کسی نے نہیں لکھا تھا۔ آب حیات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے آزاد نے ایک جدید طرز کی تذکرہ نگاری کا آغاز کیا۔ گنجینۂ معلومات ہونے کے علاوہ اس کتاب کی خوبی اس کی بے مثال طرزِ عبارت ہے کہ جس کی نقل کی سب کوشش کرتے آئے ہیں۔
آزادؔ نے اس کتاب کو پانچ ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ شاعر کے واقعاتِ حیات اور ان کی سرگزشت قلم بند کرنے میں آزاد کے پر لطف اوردل چسپ اسلوب بیان اور ان کی محاکاتی صلاحیتوں نے اسے بڑا دل پذیر بنا دیا ہے۔ ڈاکٹر محمد صادق لکھتے ہیں کہ ’’آب حیات محض اردو شاعری کی تاریخ ہی نہیں بلکہ ایک توانا، متحرک اور زندگی سے لبریز دستاویز ہے جو عہد ماضی کو از سر نو زندہ کرکے ہماری آنکھوں کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔‘‘
ناقدین کا کہنا ہے کہ آبِ حیات کے اسلوب میں جو نزاکت اور سادگی موجود ہے وہ بہت کم انشا پردازوں سے صادر ہوئی اور اگرچہ اس میں کئی تذکرے غلط واقعات کے ساتھ ہیں اور یہ ثابت ہوچکا ہے، مگر اس کتاب کی ادبی اہمیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔
اسی طرح دربارِ اکبری کو ایک عالیشان تصنیف کہا جاتا ہے جس میں آزاد ؔ نے بادشاہ اکبر کے عہد اور ان کے اراکینِ سلطنت کا حال درج کیا ہے۔ اس کتاب میں آزاد ؔ نے عہد اکبری کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے کہ تمام مناظر جیتی جاگتی تصاویر کی طرح آنکھوں کے سامنے آجاتے ہیں۔ اس کتاب کا ترجمہ انگریزی زبان میں بھی ہو چکا ہے۔
اور بات کی جائے نیرنگِ خیال جو کہ محمد حسین آزادؔ کے تمثیلی مضامین کا مجموعہ ہے تو اس کا اسلوب اور طرز بیان نہایت دل نشیں ہے۔ یہ۱۸۸۰ء میں دو حصّوں میں شائع ہوا۔ ان مضامین میں آزادؔ نے تمثیل نگاری سے کام لیا ہے۔ یہ مضامین ہلکی پھلکی اور شگفتہ مضمون نگاری کا عمدہ نمونہ ہیں۔ ان میں آزاد ؔ نے انگریزی ادب سے بھر پور استفادہ کیا ہے۔
ان کے علاوہ سخندانِِ فارس آزاد کے مختلف مقالات کا مجموعہ ہے جو فارسی زبان و ادب سے متعلق ہیں۔ فارسی ادب کے تعلق سے یہ کتاب بہت ہی دل چسپ ہے جس کے دو حصّے ہیں۔ ایک کتاب نگارستانِ فارس بھی ہے جو ایران اور ہندوستان کے فارسی شعراء کا ایک مختصر تذکرہ ہے۔
آزاد نے نہ صرف اردو نثر کو نیا انداز دیا بلکہ اردو نظم کو بھی ایک نئی شکل و صورت عطا کی تھی۔ انھوں نے تذکرہ نگاری میں منفرد اور اچھوتا انداز اپنایا اور نئی تنقید کی شمع روشن کی۔ محمد حسین آزادؔ 5 مئی 1830ء کو دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ جب چار برس کے تھے تو والدہ کا انتقال ہو گیا اور پھر والد کی شہادت ہوئی۔ بعد میں لاہور میں انھیں دو بڑے صدمات مزید سہنا پڑے اور وہ مخبوط الحواس ہوگئے۔ ان کی زندگی کے آخری کئی برس جنون اور دیوانگی کی حالت میں گزرے۔ اس کی وجہ اہلیہ اور بیٹی کی ناگہانی موت کا صدمہ تھا اور 22 جنوری 1910ء کو لاہور ہی میں انتقال کر گئے۔ ان کا مزار داتا گنج کے قریب ہے۔