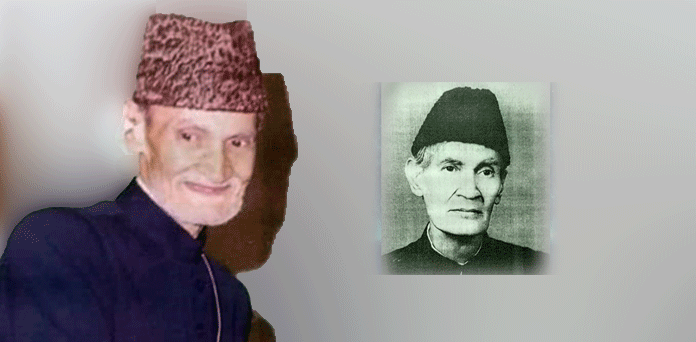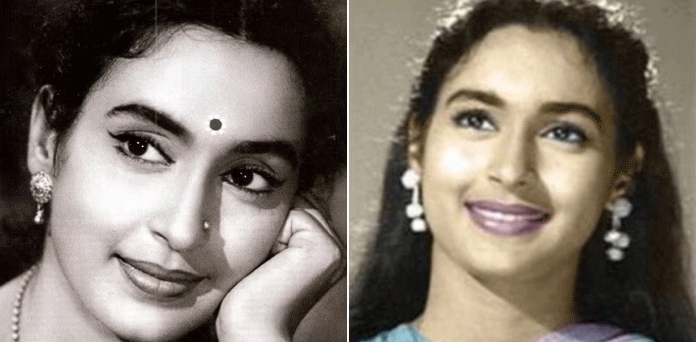گزشتہ صدی میں اسّی کی دہائی میں بڑی اسکرین پر سلطان راہی چھائے ہوئے تھے۔ گنڈاسا تھامے سلطان راہی کے مقابلے پر کوئی اور زبردست نظر ہی نہیں آتا تھا، لیکن پھر ایک حادثۂ جاںکاہ پیش آیا اور فلمی دنیا کے اس زور آور کے قدم اکھڑ گئے۔ 9 جنوری 1996ء کو اداکار سلطان راہی کے قتل کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی اور ملک بھر میں فضا سوگوار ہوگئی۔
پنجابی فلموں کے سلطان نے اس دنیا سے کوچ کیا تو اُن کی 54 فلمیں زیرِ تکمیل تھیں جو ایک ریکارڈ ہے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ پاکستان میں سلطان راہی اور بھارت میں وریند ایکشن فلموں کی جان تھے اور دونوں ہی اندھی گولیوں کا نشانہ بنے۔ وریندر بھارتی فلم انڈسٹری کے مشہور ہیرو دھرمیندر کے کزن تھے۔
فروری 1979ء میں نام وَر فلم ساز سرور بھٹی اور ہدایت کار یونس ملک کی فلم ’مولا جٹ‘ بڑے پردے پر نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ اس فلم میں دو مرکزی کردار سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی کے تھے۔ سلطان راہی نے فلم میں نیک سیرت انسان اور مصطفیٰ قریشی نے ایک بدمعاش کا کردار نبھایا تھا۔ اس فلم نے کام یابی کا وہ ریکارڈ قائم کیا جس کی انڈسٹری میں مثال نہیں ملتی۔ باکس آفس پر فلم اس قدر ہٹ ہوئی کہ مسلسل ڈھائی سال زیرِ نمائش رہی اور لوگوں نے متعدد بار بڑے پردے پر فلم دیکھی۔
مشہور فلمی رسالہ "شمع” (نئی دہلی) میں "ستاروں کی دنیا” کے عنوان سے یونس دہلوی کا مقبولِ عام کالم "مسافر” کے قلمی نام سے شایع ہوتا تھا۔ انھوں نے 1990ء کے شمارے میں اپنے اس کالم میں پاکستان کی مشہور فلم "مولا جٹ” کا ذکر کیا تھا۔ یونس دہلوی لکھتے ہیں:
"10 مارچ 1990ء کو مسافر کا اچانک ہی لاہور جانا ہو گیا۔ دانہ پانی کا اٹھنا سنتے تھے، مگر اس روز مسافر اس محاورے پر پورا ایمان لے آیا۔ اس وقت پاکستان کے شہرۂ آفاق فلم ساز سرور بھٹی کی شہرۂ آفاق فلم "مولا جٹ” کی نمائش کا موقع تھا۔”

"ہندوستان میں اگر ریکارڈ توڑ فلم "شعلے” بنی ہے تو پاکستان میں ریکارڈ توڑ ہی نہیں کرسی توڑ فلم "مولا جٹ” بنی۔ کرسی توڑ اس لیے کہ ‘مولا جٹ’ لاہور میں مشترکہ 216 ویں ہفتہ میں چل رہی تھی کہ حکومتِ وقت نے اس پر پابندی لگا کر اتار دیا۔”
"مولاجٹ 9 فروری 1979ء کو لاہور کے شبستان سنیما میں ریلیز ہوئی تھی اور 3 فروری 1981ء کو 104 ویں ہفتہ میں تھی کہ اس طرح سنیما سے اُچک لی گئی جیسے باغ میں کھلنے والا سب سے خوب صورت پھول اچک لیا جاتا ہے۔”
"بات کورٹ کچہری تک گئی۔ ہائی کورٹ نے 27 دن کی کارروائی کے بعد 55 صفحات پر مشتمل فیصلہ دیا اور حکومت کے اس فعل کو غیر قانونی قرار دیا۔”
"25 اپریل 1981ء کو "مولا جٹ” کو پھر سے کرسیاں توڑنے اور ریکارڈ توڑنے کے لیے آئے ہوئے ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ اچانک 18 مئی 1981ء کو مارشل لا قوانین کے تحت فلم کی نمائش پر پابندی لگا دی گئی۔ اس طرح ‘مولا جٹ’ کی آزادی ختم ہو گئی۔”
"پاکستان سے مارشل لا گیا تو سرور بھٹی نے ‘مولا جٹ’ کی حبسِ بے جا کے خلاف عدالت کے دروازے کھٹکھٹائے اور 9 مارچ 1990ء کو ایک بار پھر ‘مولا جٹ’ کا راج آ گیا۔ اس بار ‘مولا جٹ’ لاہور کے دس سنیما گھروں میں ایک ساتھ ریلیز کی گئی۔”
یونس دہلوی آگے لکھتے ہیں، "‘مولا جٹ’ چوں کہ ریکارڈ توڑ اور کرسی توڑ فلم تھی اس لیے منٹ منٹ پر تالیاں اور سیٹیاں بج رہی تھیں۔”
سلطان راہی کا اصل نام سلطان محمد تھا۔ ان کا سنہ پیدائش 1934 اور جائے پیدائش پاکستان کا شہر راولپنڈی ہے۔ اداکار کا تعلق مذہبی گھرانے سے تھا۔ سلطان راہی نے ابتدائی تعلیم و تربیت کے ساتھ قرآنِ پاک مع تفسیر پڑھا۔ کم عمری میں سلطان راہی کو فلموں میں دل چسپی پیدا ہوگئی اور یہ شوق اتنا بڑھا کہ وہ فلم میں کام کرنے کا خواب دیکھنے لگے۔ اسی شوق کے ہاتھوں ایک روز راولپنڈی سے لاہور چلے آئے اور اسٹیج ڈراموں سے اپنی فنی زندگی کا آغاز کیا۔ سلطان راہی نے جس ڈرامے میں پہلی مرتبہ مرکزی کردار نبھایا وہ ’شبنم روتی رہی‘ تھا۔ اس ڈرامے کے بعد ان کی رسائی فلم نگری تک ہوئی اور وہ ایکسٹرا کے کردار نبھانے لگے۔ پاکستانی فلم انڈسٹری میں اس وقت سنتوش کمار، درپن، لالہ سدھیر، مظہر شاہ کا بڑا نام تھا۔ ایکسٹرا کے طور پر کام کرتے ہوئے سلطان راہی کو بڑے کردار کی تلاش تھی۔ باغی، ہیرسیال اور چند دیگر فلموں میں ایکسٹرا کا کردار ادا کرنے کے بعد وہ ایم سلیم کی پنجابی فلم ’امام دین گوہاویا‘ میں ایک مختصر کردار ادا کرنے میں کام یاب ہوگئے۔ اسی زمانے میں ان کی وہ فلمیں بھی ریلیز ہوئیں جن میں سلطان راہی نے معمولی کردار ادا کیے تھے۔ 1971ء میں سلطان راہی کو ہدایت کار اقبال کاشمیری کی فلم ’بابل‘ میں ایک بدمعاش کا ثانوی کردار ملا اور یہی ان کی فلمی زندگی میں بڑی تبدیلی کا سبب بن گیا۔
برصغیر پاک و ہند کی پنجابی زبان میں فلمیں لاہور کے علاوہ کولکتہ اور ممبئی میں بھی بنائی جاتی رہیں اور تقسیم سے پہلے ریلیز ہوئیں لیکن ہیر رانجھا کو لاہور میں بننے والی پہلی ناطق پنجابی فلم کہا جاتا ہے۔ ابتدائی دور کی پنجابی فلمیں ہلکی پھلکی رومانوی اور نغماتی فلمیں ہوتی تھیں جو عام طور پر پنجاب کی خالص لوک داستانوں سوہنی مہینوال، مرزا صاحباں، سہتی مراد اور دلا بھٹی کے علاوہ ہندوؤں کی دیو مالائی داستانوں اور بدیسی قصے کہانیوں پر مبنی ہوتی تھیں۔
پچاس کی دہائی میں پاکستان میں پنجابی فلمیں بننے لگیں جن میں عام طور پر رومانوی اور نغماتی فلموں کے علاوہ معاشرتی موضوعات کو فلمایا گیا تھا۔ اس دور میں بہت بڑی بڑی پنجابی فلمیں سامنے آئیں۔ لیکن پھر زمانہ بدل گیا اور کہتے ہیں کہ وحشی جٹ سے پنجابی فلموں میں گنڈاسا کلچر شروع ہوا۔
اب سماجی اور رومانی فلموں کی جگہ پُرتشدد مناظر اور ایکشن سے بھرپور فلمیں شائقین کی توجہ کا مرکز بن رہی تھیں۔ 1979 میں پاکستانی فلمی صنعت میں انقلابی تبدیلی فلم ساز سرور بھٹی اور ہدایت کار یونس ملک کی فلم ’مولا جٹ‘ کی صورت میں آئی۔ اس فلم نے باکس آفس پر کام یابیوں کے تمام اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ دیے۔ اس فلم کی نمائش ضیا الحق کے مارشل لا کے دوران ہوئی تھی جس کا ذکر یونس دہلوی کے مضمون میں آیا ہے۔ سلطان راہی نے ستّر کی دہائی کے آغاز پر بشیرا اور وحشی جٹ جیسی فلموں سے اپنے کیریئر کی سمت تو گویا طے کرلی تھی لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کی انتہا کیا ہوگی۔ لیکن فلم مولا جٹ کی بے مثال کام یابی نے یہ طے کر دیا۔ اس کے بعد سطان راہی کی پانچ فلمیں ایک ہی دن ریلیز ہوئیں۔ یہ 12 اگست 1981ء کی بات ہے جب شیر خان، سالا صاحب، چن وریام، اتھرا پُتر اور ملے گا ظلم دا بدلہ کے نام سے فلمیں ریلیز ہوئیں اور ایک نیا ریکارڈ قائم ہوا۔ ’شیر خان‘ اور ’سالا صاحب‘ نے ڈبل ڈائمنڈ جوبلی (دو سو ہفتے) اور ’چن وریام‘ نے سنگل ڈائمنڈ جوبلی مکمل کی۔ صحافی اور محقق و ادیب عارف وقار لکھتے ہیں کہ اسّی کے عشرے میں پنجابی فلمیں حاوی نظر آئیں۔ اس دوران سلطان راہی کی آسمان کو چھوتی مقبولیت کے سبب لالی وڈ میں اردو کی 223 فلموں کے مقابلے میں پنجابی کی 370 پکچرز ریلیز ہوئیں۔ بیسویں صدی کی آخری دہائی میں جب پاکستانی فلم انڈسٹری کی کمر ٹوٹ چکی تھی اور فلمی صنعت کا شیش محل زمین بوس ہو چکا تھا تب بھی ماضی کی اس شان دار عمارت کا کچھ حصّہ ایک مضبوط ستون کے سہارے کھڑا رہ گیا تھا۔ اور یہ ستون سلطان راہی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، جو پچاس کی دہائی میں ایک ایکسٹرا بوائے کے طور پر آیا تھا اور ترقی کی منازل طے کرتا ہوا پہلے ولن اور پھر ہیرو کے طور پر ساری صنعت پر چھا گیا تھا۔ لیکن اس کی موت سے وہ آخری ستون بھی کھسک گیا اور فلمی صنعت کی رہی سہی عمارت ملبے کا ڈھیر بن گئی۔
صحافی اور محقق و ادیب عارف وقار لکھتے ہیں کہ اسّی کے عشرے میں پنجابی فلمیں حاوی نظر آئیں۔ اس دوران سلطان راہی کی آسمان کو چھوتی مقبولیت کے سبب لالی وڈ میں اردو کی 223 فلموں کے مقابلے میں پنجابی کی 370 پکچرز ریلیز ہوئیں۔ بیسویں صدی کی آخری دہائی میں جب پاکستانی فلم انڈسٹری کی کمر ٹوٹ چکی تھی اور فلمی صنعت کا شیش محل زمین بوس ہو چکا تھا تب بھی ماضی کی اس شان دار عمارت کا کچھ حصّہ ایک مضبوط ستون کے سہارے کھڑا رہ گیا تھا۔ اور یہ ستون سلطان راہی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، جو پچاس کی دہائی میں ایک ایکسٹرا بوائے کے طور پر آیا تھا اور ترقی کی منازل طے کرتا ہوا پہلے ولن اور پھر ہیرو کے طور پر ساری صنعت پر چھا گیا تھا۔ لیکن اس کی موت سے وہ آخری ستون بھی کھسک گیا اور فلمی صنعت کی رہی سہی عمارت ملبے کا ڈھیر بن گئی۔
اداکار سلطان راہی کو لاہور میں شاہ شمس قادری کے مزار کے احاطے میں سپردِ خاک کیا گیا۔
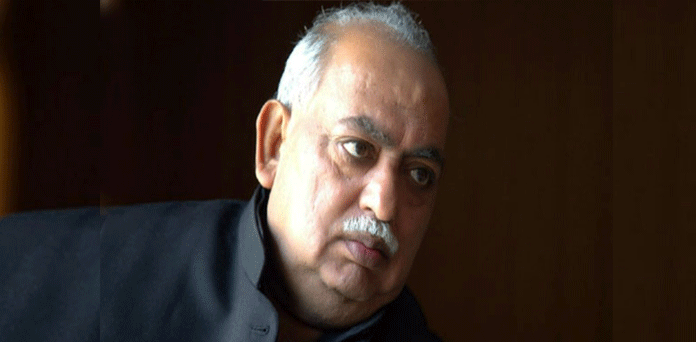
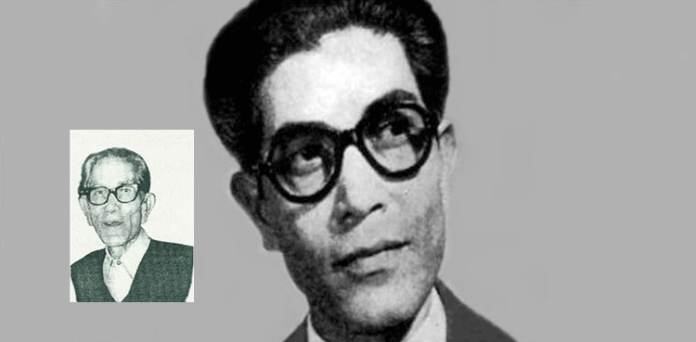
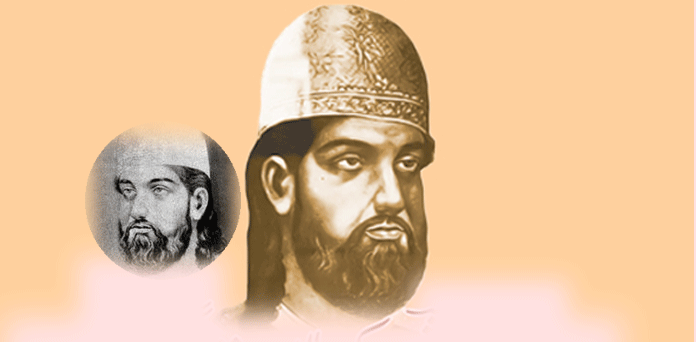
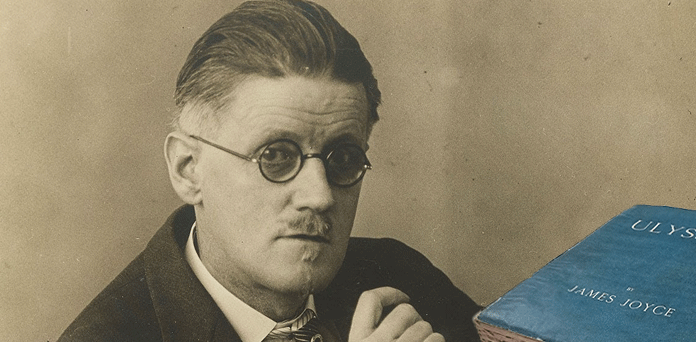
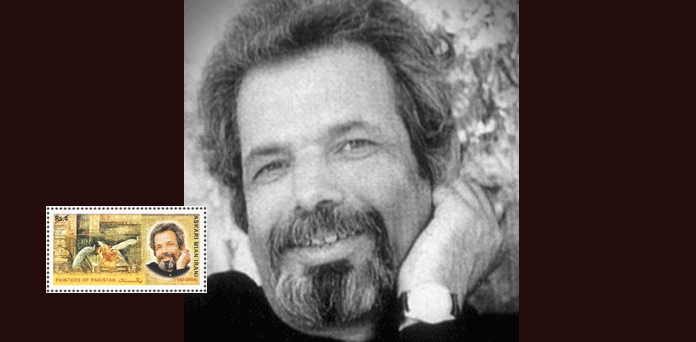
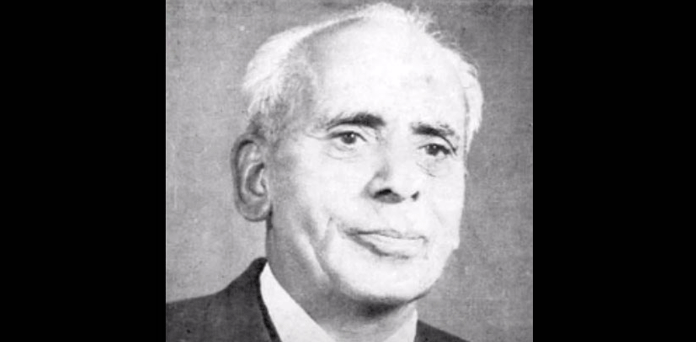



 صحافی اور محقق و ادیب عارف وقار لکھتے ہیں کہ اسّی کے عشرے میں پنجابی فلمیں حاوی نظر آئیں۔ اس دوران سلطان راہی کی آسمان کو چھوتی مقبولیت کے سبب لالی وڈ میں اردو کی 223 فلموں کے مقابلے میں پنجابی کی 370 پکچرز ریلیز ہوئیں۔ بیسویں صدی کی آخری دہائی میں جب پاکستانی فلم انڈسٹری کی کمر ٹوٹ چکی تھی اور فلمی صنعت کا شیش محل زمین بوس ہو چکا تھا تب بھی ماضی کی اس شان دار عمارت کا کچھ حصّہ ایک مضبوط ستون کے سہارے کھڑا رہ گیا تھا۔ اور یہ ستون سلطان راہی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، جو پچاس کی دہائی میں ایک ایکسٹرا بوائے کے طور پر آیا تھا اور ترقی کی منازل طے کرتا ہوا پہلے ولن اور پھر ہیرو کے طور پر ساری صنعت پر چھا گیا تھا۔ لیکن اس کی موت سے وہ آخری ستون بھی کھسک گیا اور فلمی صنعت کی رہی سہی عمارت ملبے کا ڈھیر بن گئی۔
صحافی اور محقق و ادیب عارف وقار لکھتے ہیں کہ اسّی کے عشرے میں پنجابی فلمیں حاوی نظر آئیں۔ اس دوران سلطان راہی کی آسمان کو چھوتی مقبولیت کے سبب لالی وڈ میں اردو کی 223 فلموں کے مقابلے میں پنجابی کی 370 پکچرز ریلیز ہوئیں۔ بیسویں صدی کی آخری دہائی میں جب پاکستانی فلم انڈسٹری کی کمر ٹوٹ چکی تھی اور فلمی صنعت کا شیش محل زمین بوس ہو چکا تھا تب بھی ماضی کی اس شان دار عمارت کا کچھ حصّہ ایک مضبوط ستون کے سہارے کھڑا رہ گیا تھا۔ اور یہ ستون سلطان راہی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، جو پچاس کی دہائی میں ایک ایکسٹرا بوائے کے طور پر آیا تھا اور ترقی کی منازل طے کرتا ہوا پہلے ولن اور پھر ہیرو کے طور پر ساری صنعت پر چھا گیا تھا۔ لیکن اس کی موت سے وہ آخری ستون بھی کھسک گیا اور فلمی صنعت کی رہی سہی عمارت ملبے کا ڈھیر بن گئی۔