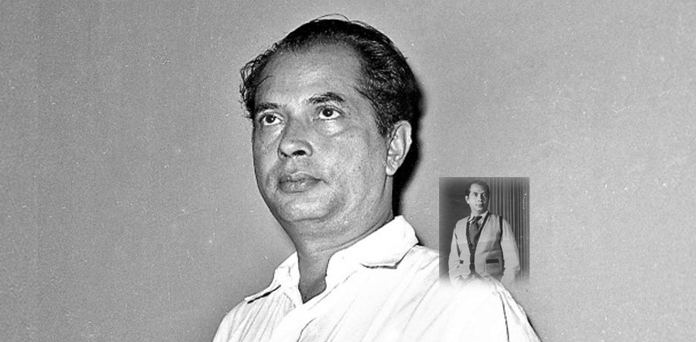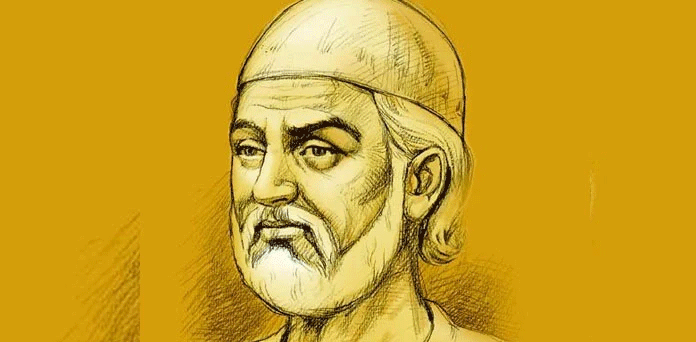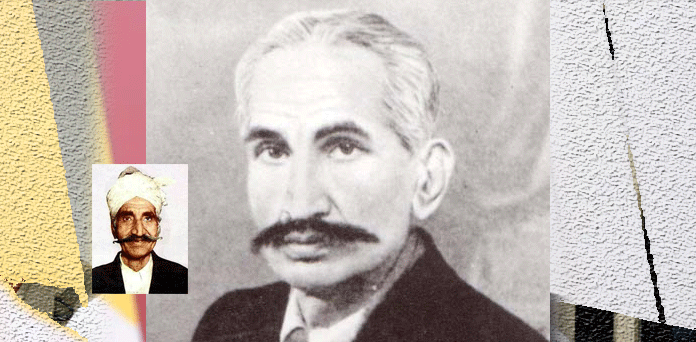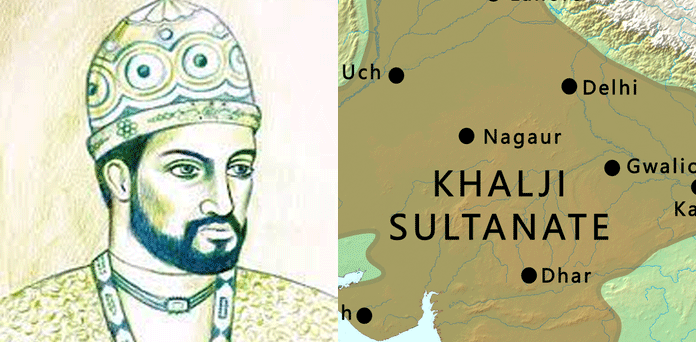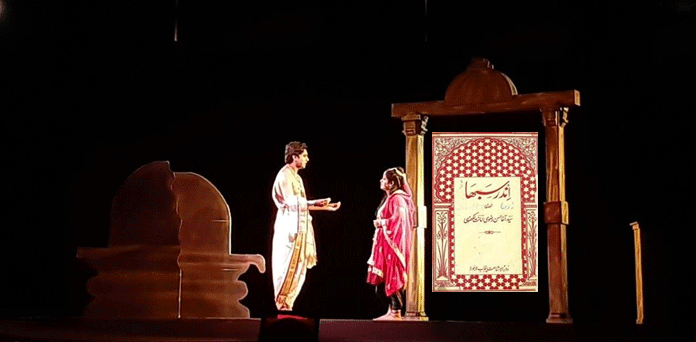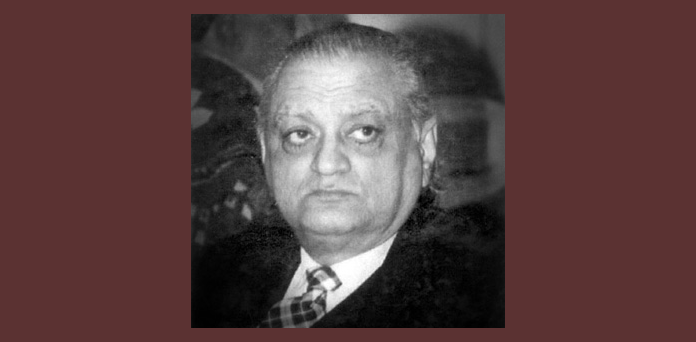ایک دور تھا جب متحدہ ہندوستان میں آرٹ سنیما کو کئی باکمال اور بے حد منجھے ہوئے فن کار میسر تھے۔ ان میں کئی نام ایسے تھے جو فن و تخلیق کے ساتھ بلند فکر اور اعلیٰ صفات کے حامل تھے۔ ان بلند فکر اور وسیع المشرب فلم سازوں نے ہندوستانی سنیما کو بے مثال فلمیں ہی نہیں دیں بلکہ ان کا کام انڈسٹری میں نئے آنے والوں کے لیے مِیل کا پتھر ثابت ہوا۔
ہندوستانی سنیما میں بمل رائے نے ایک عظیم فن کار اور باکمال ہدایت کار کے طور پر شہرت پائی جو اعلیٰ انسانی اقدار پر یقین رکھتے تھے۔ وہ بامقصد تفریح کے قائل بمل رائے 1966ء میں آج ہی کے روز ممبئی میں انتقال کر گئے تھے۔
بمل رائے کا تعلق سو پور سے تھا جو آج بنگلہ دیش کا حصّہ ہے۔ ہدایت کار بمل رائے 1909ء میں ایک زمین دار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ والد کی وفات کے بعد ان پر کنبے کی ذمہ داریاں آن پڑیں اور بمل رائے کو معاش کی فکر ستانے لگی۔ وہ کام کی تلاش میں کولکتہ چلے گئے جہاں اس وقت بڑی بڑی فلمیں بنائی جارہی تھیں۔ وہاں نیو تھیٹرز لمیٹڈ کے ساتھ کیمرا اسسٹنٹ کے طور پر کام کیا۔ اور 1935 میں بننے والی فلم ’’دیو داس‘‘میں ہدایت کار پی سی بوروا کے اسسٹنٹ کی حیثیت سے کام کرنے کا موقع مل گیا۔ 1940ء کی دہائی میں کولکتہ کی فلمی صنعت کا زور ٹوٹ گیا اور بِمل رائے 1950 میں ممبئی شفٹ ہو گئے۔ بمل رائے باصلاحیت اور ذہین بھی تھے۔ ہدایت کاری سے قبل بطور فوٹو گرافر فلم انڈسٹری میں کام کا تجربہ حاصل کرچکے تھے اور جب قسمت نے یاوری کی تو اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی حیثیت سے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہوئے بہت کچھ سیکھا۔ بمبئی میں بمل رائے نے اپنے فنی اور تخلیقی سفر کو منوایا اور بڑے ہدایت کاروں میں ان کا شمار ہوا۔
بمل رائے نے اپنی علمیت اور فن کارانہ صلاحیت کا خوب تال میل بنایا اور انڈسٹری کو سماجی موضوعات پر شان دار فلمیں دیں۔ وہ ایک نظریاتی آدمی تھے اور اُن کا جھکاؤ سوشلزم کی طرف تھا۔ بمل رائے کی فلموں میں پسے ہوئے طبقات اور استحصال زدہ لوگوں کی عکاسی کی گئی۔ ذات پات کے سخت مخالف بمل رائے کا شیوہ انسانیت پرستی رہی اور ان کی فلموں میں اُن کے خیالات اور نظریات کی واضح تصویریں ہم دیکھتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دو بیگھہ زمین ہے۔
دو بیگھہ زمین بِمل رائے ان کی وہ فلم تھی جس نے زمین داروں اور ساہو کاروں کے ساتھ ایک کسان کی زندگی کو پردے پر پیش کیا۔ اس فلم نے تہلکہ مچا دیا۔ انھیں عالمی فلمی میلے اور مقامی فلمی صنعت کے کئی ایوارڈ دیے گئے۔ اس فلم کو کلاسیک کا درجہ حاصل ہے۔ ہدایت کار بِمل رائے کے بارے میں مشہور تھا کہ ایک سین کو اس وقت تک عکس بند کرواتے ہیں جب تک پوری طرح مطمئن نہ ہوجائیں۔ اس سے فلمیں اوور بجٹ ہوجاتی تھیں۔ لیکن نہایت خوب اور تکمیلیت پسندی کی اس عادت نے ان سے کئی شان دار فلمیں بنوائی ہیں۔ اس کی ایک مثال فلم ’مدھو متی‘ ہے جسے بِمل رائے نے ایک ہی سین کی کئی عکس بندیوں کی وجہ سے اوور بجٹ کردیا تھا اور مالی خسارے سے بچانے کے لیے دلیپ کمار اور ڈسٹری بیوٹروں نے بمل رائے کے لیے بڑی قربانی دی تھی۔ ’مدھو متی‘ سپرہٹ ثابت ہوئی اور اسے بہترین فیچر فلم، بہترین فلم اور بمل رائے کو بہترین ہدایت کار کا ایوارڈ بھی دیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ فلم فیئر ایوارڈ میں ’مدھو متی‘ نے 13 نام زدگیوں کے ساتھ 9 ایوارڈز اپنے نام کیے۔ ’’بندنی‘‘بھی بِمل رائے کے فن و تخلیق کا ایک بیّن ثبوت ہے۔ یہ فلم بِمل رائے کے سوشلسٹ نظریات کی عکاس تھی۔ اس فلم میں یہ ثابت کرنے کی بھی کوشش کی کہ ایک سچا سوشلسٹ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اپنے راستے سے ہٹ سکتا ہے۔
اس عظیم ہدایت کار نے اپنی فلموں کے ذریعے ہندوستان میں سماجی انقلاب لانے کی کوشش کی اور ناانصافیوں کی نشان دہی کرتے رہے۔ ان کا شمار فلم کی چکاچوند اور جگمگاتی ہوئی دنیا میں اپنے مقصد کو فراموش کر کے شہرت اور دولت کے پیچھے بھاگنے والوں میں نہیں ہوتا بلکہ پیسے سے زیادہ وہ مقصد کو اہمیت دیتے تھے۔
اپنے وقت کے کئی فلمی ستاروں نے بمل رائے کے ساتھ کام کیا اور جو نہیں کرسکے انھیں اس بات کا ملال ضرور رہا کہ وہ اس عظیم ہدایت کار کی فلم میں کام نہ کرسکے۔ معروف بنگالی اداکارہ کانن دیوی نے ایک بار بمل رائے سے کہا تھا: ’ارے بمل دا آپ کے ہاتھوں میں تو جادو ہے۔ آپ نے تو مجھے اپسرا بنا دیا۔
پرنیتا، دیو داس، سجاتا، پرکھ، بندنی ودیگر بمل رائے کی شان دار فلمیں ہیں۔