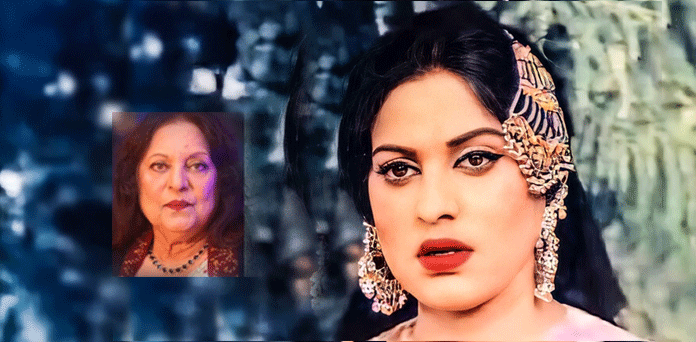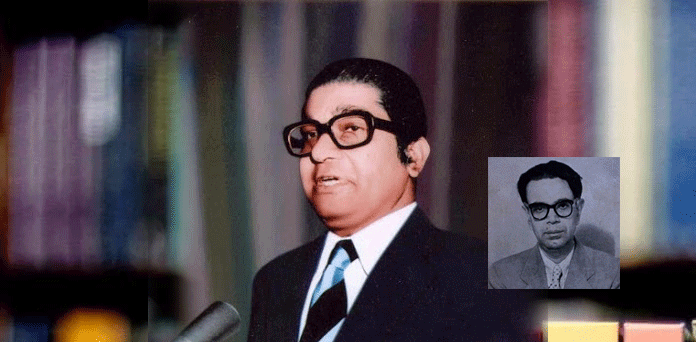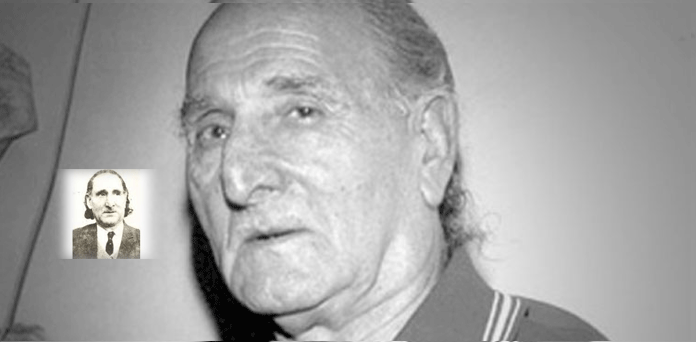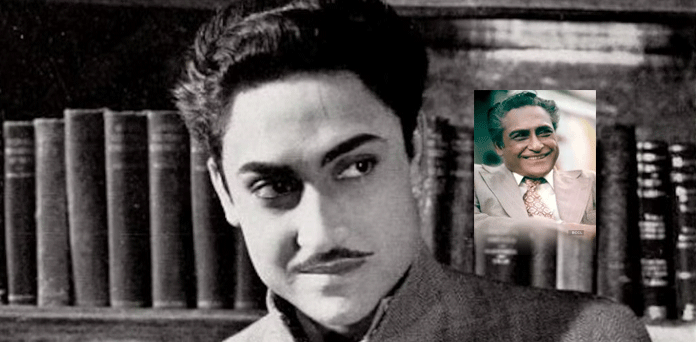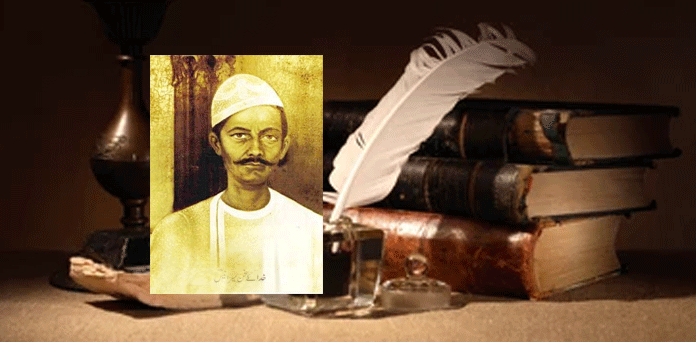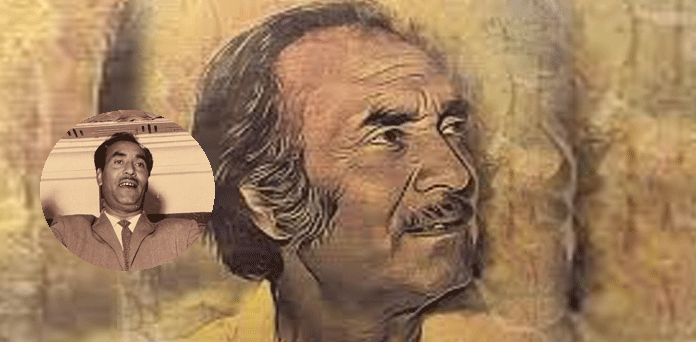میر انیس کا نام اردو شاعری میں بطور مرثیہ نگار ہمیشہ زندہ رہے گا۔ وہ اس فن کے بادشاہ کہلائے اور یہی حقیقت بھی ہے کہ اس صنفِ شاعری کو میر انیس کے بعد آج تک نہ تو حوالہ و سند کے لیے کسی دوسرے شاعر کی ضرورت محسوس ہوئی اور نہ ہی اس صنف میں کمال و فن نے اس پائے کا کوئی شاعر دیکھا۔ مرثیہ نگاری کو عروج بخشنے والے میر انیس کے مراثی برصغیر میں ہر مجلس اور ہر محفل میں آج بھی پڑھے جاتے ہیں۔
آج میر انیس کی برسی ہے۔ میر انیس نے اپنے مرثیوں میں کربلا میں حق و باطل کے مابین جنگ کا نقشہ اور حالات و واقعات کا تذکرہ اس کیا ہے کہ سننے اور پڑھنے والے کی آنکھوں میں اس کی تصویر بن جاتی ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ سب اس کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ ان کا طرزِ بیان بہت مؤثر اور دل گداز ہے۔ انیس نے صرف جنگ کے ہی مناظر نہیں بلکہ میدان اور فطری مناظر کی ایسی لفظی تصویریں بنائی ہیں کہ آئندہ بھی اس کی مثال دی جاتی رہے گی۔
میر انیس نے باقاعدہ شاعری کا آغاز غزل گوئی سے کیا تھا۔ لیکن پھر منقبت اور مرثیہ کی صنف کو اپنایا اور بڑا نام پیدا کیا۔ برصغیر کا یہ عظیم مرثیہ نگار ایک نازک مزاج اور بڑی آن بان والا بھی تھا۔ وہ امیروں اور رئیسوں کی صحبت سے دور رہے۔ چاہتے تو اودھ کے دربار میں ان پر بڑی نوازش اور تکریم ہوتی مگر وہ ایک فقیر صفت اور اپنے حال میں رہنے والے انسان تھے۔
میر انیس کا حقیقی نام میر ببر علی تھا۔ وہ 1803ء عیسوی میں اتر پردیش کے شہر فیض آباد کے ایک ادبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ والد میر مستحسن خلیق اور پر دادا میر ضاحک اپنے دور کے استاد شاعر تھے۔ دادا میر حسن اردو ادب کے معروف مثنوی گو شاعر تھے۔ یہ وہی میر حسن ہیں جنھوں نے اردو ادب کو مثنوی ‘سحر البیان’ دی۔ یوں کہیے کہ شاعری میر انیس کی گھٹی میں پڑی تھی۔ وہ پانچ چھ برس کی عمر سے ہی شعر موزوں کرنے لگے تھے۔
میر انیس غزل گوئی اور مرثیہ گوئی میں اپنے والد میر خلیق کے شاگرد تھے۔ کبھی کبھی اپنے والد کے کہنے پر شیخ امام بخش ناسخ کو بھی اپنی غزلیں دکھا لیا کرتے تھے اور انہی کے کہنے پر انیس کا تخلص اپنایا۔
یہاں ہم اس غزل کے چند اشعار پیش کررہے ہیں جو میر انیس نے ایک مشاعرہ میں پڑھی تھی اور ہر طرف ان کی دھوم مچ گئی۔ اشعار یہ ہیں۔
اشارے کیا نگۂ نازِ دل ربا کے چلے
ستم کے تیر چلے نیمچے قضا کے چلے
مثال ماہیٔ بے آب موجیں تڑپا کیں
حباب پھوٹ کے روئے جو تم نہا کے چلے
کسی کا دل نہ کیا ہم نے پائمال کبھی
چلے جو راہ تو چیونٹی کو بھی بچا کے چلے
لیکن پھر وہ مرثیہ گوئی کی طرف آنکلے اور یہی صنف ان کی لازوال پہچان بنی۔ ہندوستان کے ممتاز ادیب، نقاد اور شاعر شمس الرّحمٰن فاروقی نے اپنے ایک مضمون میں میر انیس کے بارے میں لکھا، "میں میر انیس کو ہمیشہ سے چار پانچ بڑے شاعروں میں رکھتا ہوں۔ بنیادی بات رواں کلام ہے۔ یہ بہت بڑی صفت ہے۔ ہم اس کو سمجھ اور قدر نہیں کر پائے۔ خیر، یہ سمجھنے والی بات بھی نہیں محسوس کرنے کی بات ہے۔ مصرع کتنا مشکل ہو۔ کتنا عربی فارسی ہو، کتنا ہندی سندھی ہو، آسانی اور روانی سے ادا ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آجاتا ہے۔
مصرع میں لگتا نہیں لفظ زیادہ ہوگیا ہے یا کم ہوگیا۔ میر انیس کا شاعری میں یہ کمال اپنی جگہ ہے کہ الفاظ کو اپنے رنگ میں ڈھال لیتے ہیں، کسی سے یہ بن نہیں پڑا۔ مضمون ایک ہے، لیکن ہر مرثیہ نیا معلوم ہوتا ہے۔ زبان پر غیر معمولی عبور۔ زبان عام طور پر شاعر پر حاوی ہوتی ہے لیکن میر انیس زبان پرحاوی ہے۔ معمولی مصرع بھی کہیں گے توایسی بات رکھ دیں گے کہ کوئی دوسرا آدمی کہہ نہیں سکتا۔ اکثر یہ تو آپ تجزیہ کرکے دکھا سکتے ہیں کہ اس غزل یا نظم میں کیا کیا ہے، میر انیس کے معاملہ میں نہیں دکھا سکتے۔”
اسی طرح نیر مسعود جیسے بڑے ادیب اور افسانہ نگار لکھتے ہیں کہ "انیس کی مستند ترین تصویر وہ ہے جو ان کے ایک قدر دان نے کسی باکمال مصور سے ہاتھی دانت کی تختی پر بنوا کر ان کو پیش کی تھی۔ انیس کی جو تصویریں عام طور پر چھپتی رہتی ہیں وہ اسی ہاتھی دانت والی تصویر کا نقش مستعار ہیں۔ لیکن ان نقلوں میں اصل کے مو قلم کی باریکیاں نہیں آسکیں۔ اصل تصویر میں میر کی غلافی آنکھیں، آنکھوں کے نیچے باریک جھریاں، رخساروں کی ہڈیوں کا ہلکا سا ابھار، ذرا پھیلے ہوئے نتھنے اور بھنچے ہوئے پتلے پتلے ہونٹ مل کر ایک ایسے شخص کا تاثر پیدا کرتے ہیں جو بہت ذکی الحس اور ارادے کا مضبوط ہے۔ دنیا کو ٹھکرا دینے کا نہ صرف حوصلہ رکھتا ہے بلکہ شاید ٹھکرا چکا ہے۔ وہ کسی کو اپنے ساتھ زیادہ بے تکلف ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا اور کسی سے مرعوب نہیں ہوسکتا۔ اور اس کی خاموش اور بہ ظاہر پر سکون شخصیت کی تہ میں تجربات اور تاثرات کا ایک طوفان برپا ہے۔”
یہاں ہم ایک شعر سے متعلق وہ دل چسپ واقعہ بھی نقل کررہے ہیں جو ادبی تذکروں میں پڑھنے کو ملتا ہے۔ ملاحظہ کیجیے: میر انیس نے ایک مرثیے میں دعائیہ مصرع لکھا۔ ”یارب رسولِ پاک کی کھیتی ہری رہے“ مگر خاصی دیر تک دوسرا مصرع موزوں نہ کرسکے۔ وہ اِس مصرع کو شعر کرنے کی فکر میں ڈوبے ہوئے تھے کہ ان کی اہلیہ سے نہ رہا گیا، وہ ان سے پوچھ بیٹھیں کہ کس سوچ میں ہیں؟ میر انیس نے بتایا تو بیوی نے بے ساختہ کہا یہ لکھ دو، ”صندل سے مانگ، بچوں سے گودی بھری رہے“، میر انیس نے فوراً یہ مصرع لکھ لیا اور یہی شعر اپنے مرثیے میں شامل کیا۔ ادبی تذکروں میں آیا ہے کہ مرثیے کے اس مطلع کا پہلا مصرع میر انیس کا دوسرا ان کی بیوی کا ہے۔ یہ شعر بہت مشہور ہوا اور ضرب المثل ٹھیرا۔ اور آج بھی میر انیس کا یہ دعائیہ شعر ضرور پڑھا جاتا ہے۔
اردو کے اس بے مثل شاعر نے 10 دسمبر 1874ء کو ہمیشہ کے لیے یہ دنیا چھوڑ دی تھی۔