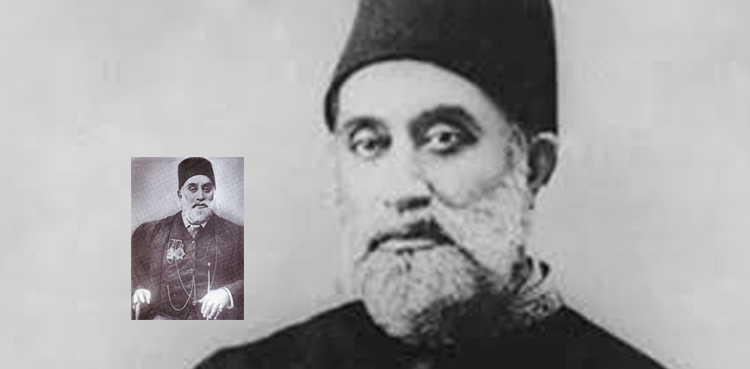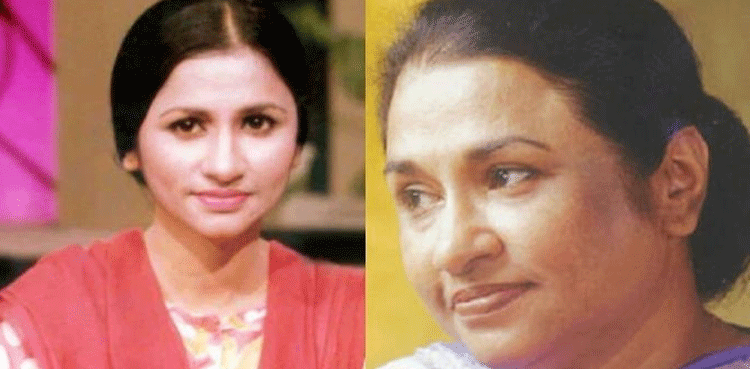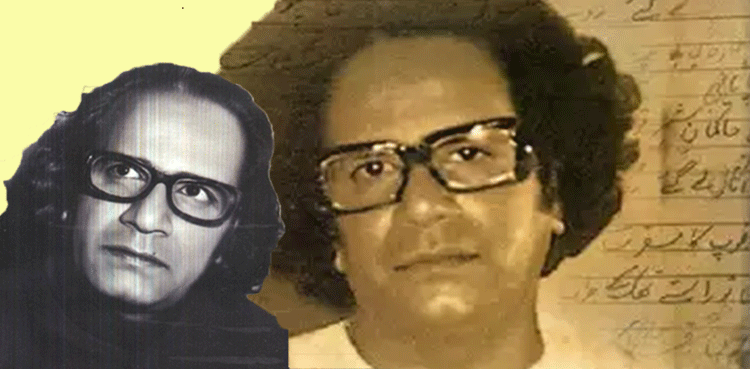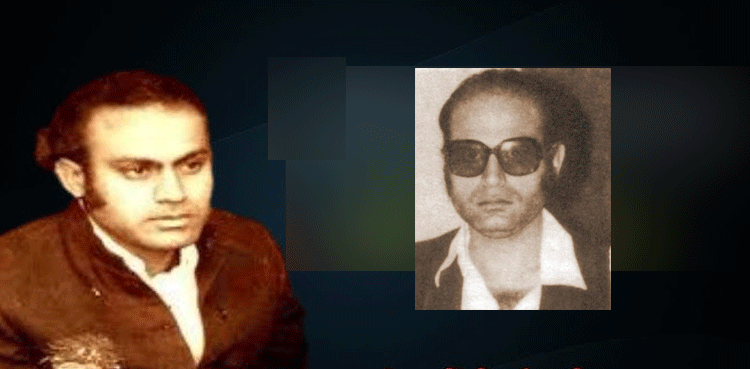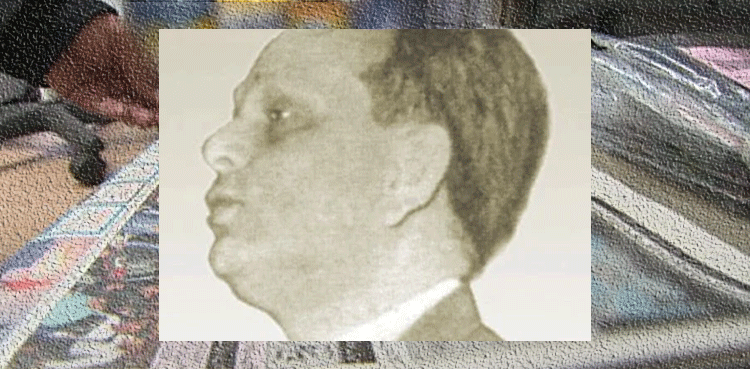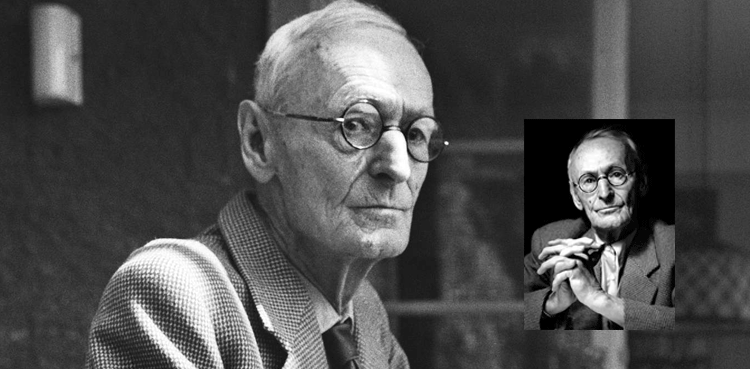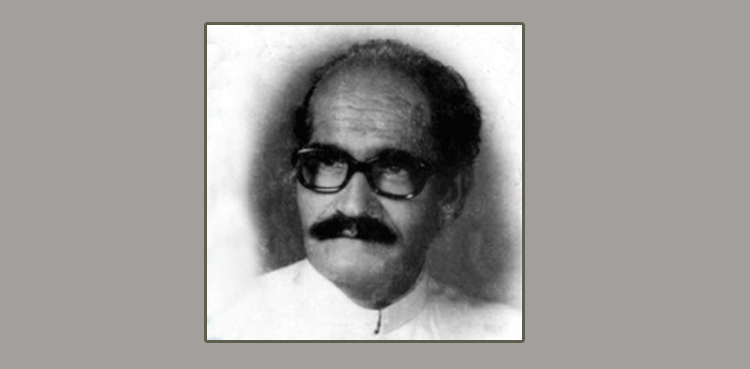حسن علی آفندی کو تاریخ ایک مدبّر اور علم دوست شخصیت کے طور پر ہمیشہ یاد رکھے گی جن کا ایک کارنامہ سندھ کے دارالخلافہ کراچی میں عظیم الشّان درس گاہ کا قیام تھا جس کے تحت ایک نسل زیورِ تعلیم سے آراستہ ہوئی اور قابل اساتذہ نے ان کی راہ نمائی اور تربیت کی۔
کراچی کی تاریخ دیکھیں تو ہمیں کئی قابل و باکمال شخصیات ایسی نظر آئیں گی جنھوں نے سندھ میں علم و ادب اور تہذیب و ثقافت کی ترویج و اشاعت میں بنیادی کردار ادا کیا اور حسن علی آفندی انہی میں سے ایک ہیں۔ سندھ مدرستہُ الاسلام کے نام سے آج ہم جس تعلیمی ادارے کو شناخت کرتے ہیں، اس کے بانی حسن علی آفندی تھے۔ انھوں نے کراچی میں فلاح و بہبود کے کئی کام کیے اور نوجوان نسل کی تعلیم و تربیت کے لیے خدمات انجام دیں۔ حسن علی آفندی 20 اگست 1895ء کو انتقال کرگئے تھے۔
وہ 14 اگست 1830ء کو سندھ کے شہر حیدرآباد کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے تھے اور غربت اور کئی مشکلات کے باوجود اپنی محنت اور لگن سے نہ صرف تعلیم حاصل کرکے اپنا مستقبل بنایا بلکہ اس دور کے نوجوانوں کو بھی ترقی اور کام یابی کے زینے طے کرنے کے لیے ایک درس گاہ کے ذریعے سہولت فراہم کی۔ اسی مدرسہ سے پاکستان کے بانی محمد علی جناح نے بھی تعلیم حاصل کی تھی۔
حسن علی آفندی نے وکالت کی تعلیم مکمل کرنے کے دوران اس راستے میں کئی مسائل اور رکاوٹوں کا سامنا کیا، اسی دوران انھیں سندھ کے مسلمان نوجوانوں کے لیے تعلیمی ادارہ بنانے کا خیال آیا۔ تب انھوں نے ہندوستان کی قابل شخصیات اور مخیّر لوگوں سے ملاقاتیں کیں اور ان کی مدد اور تعاون حاصل کرنے میں کام یاب ہوگئے۔ 1885ء میں حسن علی آفندی نے کراچی میں سندھ مدرسۃُ الاسلام کی بنیاد رکھی جو ایک اسکول تھا، بعد میں اسے کالج کا درجہ دے دیا گیا۔
حسن علی آفندی کے فلاحی کارناموں کے اعتراف میں برطانوی سرکار نے انہیں خان بہادر کا خطاب دیا تھا۔ وہ ہندوستان کی سیاست سے بھی وابستہ رہے اور آل انڈیا مسلم لیگ اور مسلم لیگ پارلیمانی بورڈ کے رکن کے طور پر کام کیا۔ 1934ء سے 1938ء تک وہ سندھ کی قانون ساز اسمبلی کے رکن بھی رہے۔
حسن علی آفندی بھی سرسید کی طرح یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں نے اگر جدید تعلیم حاصل نہ کی تو وہ ہر لحاظ سے پیچھے رہ جائیں گے اور ہندوستان کی آزادی کا خواب کبھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ سندھ مدرسہ نے ثابت کیا کہ حسن علی آفندی اور ان کے ساتھیوں کا ایک جدید درس گاہ کے قیام کا فیصلہ مسلمانوں کے وسیع تر مفاد میں تھا کیوں کہ بعد میں اسی ادارے سے بانی پاکستان قائداعظم محمد علی جناح کے علاوہ کئی ایسے مسلمان راہ نما نکلے جنھوں نے مسلمانوں کی اصلاح اور تحریک پاکستان میں مرکزی کردار ادا کیا۔