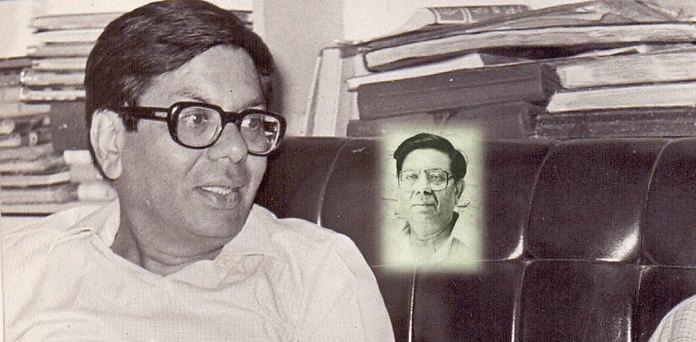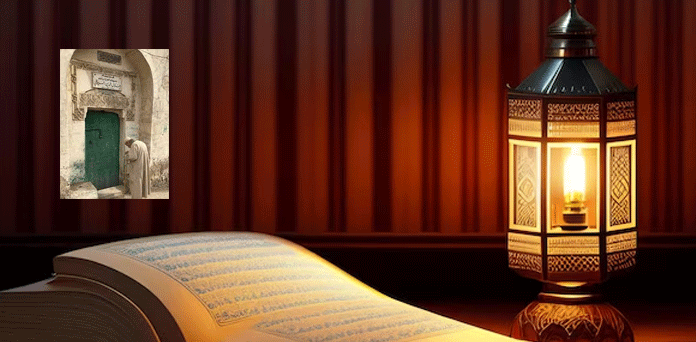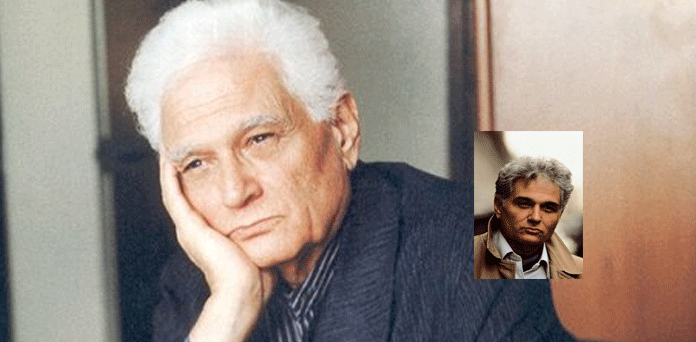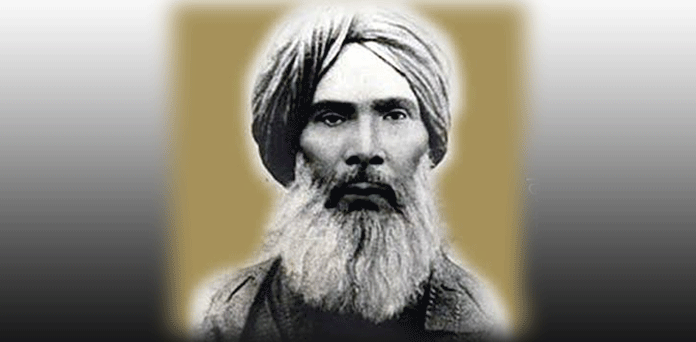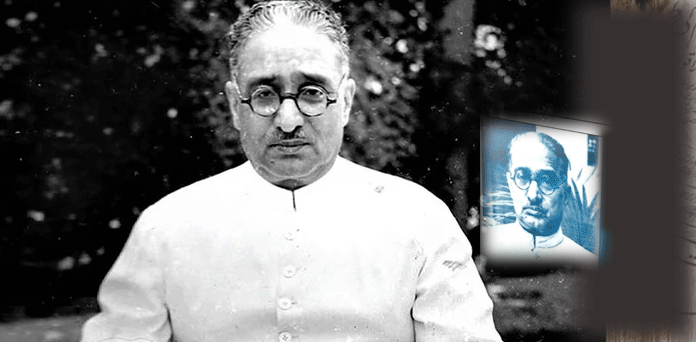ڈاکٹر خلیق انجم کا شمار ہندوستان اور اردو زبان و ادب کے صفِ اوّل کے محققین میں ہوتا تھا۔ وہ نقاد اور ماہرِ غالبیات مشہور تھے جنھوں نے مختلف اصنافِ ادب کو اپنی تحریروں سے مالا مال کیا۔
ڈاکٹر خلیق انجم سے متعلق رفعت سروش لکھتے ہیں: ’’انجمن تعمیر اردو کے جلسے ہی میں ڈاکٹر خلیق انجم سے تعارف ہوا۔ درمیانہ قد و قامت سوچتی ہوئی آنکھیں، فراخ دل چہرہ کے کشادہ خدوخال سے نمایاں آواز میں دل گداز کھوج، تیکھا لب و لہجہ مگر اس تیکھے لب و لہجے میں ہلکی سی ظرافت کی آمیزش کہ سننے والے کو ناگواری نہ ہو اور کہنے والا اپنی بات مزے سے کہہ جائے۔”
انجمن ترقّیِ اردو (ہند) دہلی کے سابق سیکریٹری اور نائب صدر کے عہدے پر فائز ڈاکٹر خلیق انجم 18 اکتوبر2016ء کو وفات پاگئے تھے۔ آج ان کی برسی ہے۔
خلیق انجم کے والد محمد احمد مرحوم ریلوے انجینئر تھے۔ ان کے نانا انگریزوں فارسی اور اردو کے عالم تھے اور کالج میں انگریزوں کو اردو سکھاتے تھے۔ ڈاکٹر خلیق انجم کی والدہ نے دہلی کے فرانسیسی گرلز ہائی اسکول میں اس زمانے میں تعلیم پائی جب مسلمان لڑکی کو تعلیم کے لیے گھر سے باہر بھیجنے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ خلیق انجم کی والدہ قیصرہ سلطانہ غیر معمولی ذہین خاتون تھیں۔ مڈل تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد شادی ہوگئی۔ خلیق انجم کی والدہ قیصرہ سلطانہ عزیزی کے نام سے اردو رسالوں میں عورتوں کے سماجی مسائل پر مضامین لکھا کرتی تھیں۔ خلیق انجم کے والد کے انتقال کے بعد والدہ نے لکھنا چھوڑ کر ملازمت شروع کر دی اور چار بیٹیوں اور ایک بیٹے کے ساتھ زندگی کی گاڑی کو کھینچنے لگیں۔ ساتھ ہی اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور پہلے استانی اور پھر ہیڈ مسٹریس بن گئیں۔
خلیق انجم کو اسکول کے زمانے سے ہی شاعری، افسانے اور ناول پڑھنے کا شوق پیدا ہوگیا تھا۔ اسکول کے میگزین کے ایڈیٹر بھی رہے اور علی گڑھ سے شائع ہونے والے ماہنامہ ’’جھلک‘‘ میں ان کے افسانے شایع ہونے لگے۔ ایم اے اردو کرنے کے بعد خلیق انجم کالج میں لیکچرر ہوگئے۔ خلیق انجم کی سب سے پہلی کتاب ’’معراج العاشقین‘‘ تھی۔ ڈاکٹر خلیق انجم کے پی ایچ ڈی کے مقالے کا موضوع ’’مرزا مظہر جان جاناں‘‘ تھا۔ پھر انھوں نے رفیع سوداؔ اپنا تحقیقی مواد انجمن ترقی اردو ہند سے شائع کروایا۔ خلیق انجم کے رشحاتِ قلم پر مشتمل 80 کتابیں اور کئی علمی و ادبی مضامین منظر عام پر آئے۔ بھارت سے تعلق رکھنے والے خلیق انجم 1935ء میں دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ اصل نام خلیق احمد خان تھا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے گریجویشن اور ایم اے (اردو) دہلی یونیورسٹی سے کیا۔
رضا علی عابدی نے ان کی وفات کے بعد اپنے کالم میں لکھا:
اور خلیق انجم کے کام کا کوئی شمار ہے؟ عمر بھر لکھتے رہے اور وہ بھی تحقیق کے جابجا بکھرے ہوئے موتی بٹور کر۔ اوپر سے یہ کہ اپنی اس ساری مشقت کو اتنے سلیقے اور ہنر مندی سے کتاب کے ورق پر بکھیر گئے کہ علم کی آنکھیں بھی منور ہوتی ہیں اور ذہن کے دریچے بھی۔ ان علم و حکمت کے جواہر کی بات ذرا دیر بعد، پہلے ان لمحات کو یاد کرلیا جائے جو میں نے خلیق انجم کے ساتھ گزارے۔
بلا شبہ خلیق انجم اردو کی تہذیبی و ثقافتی اقدار اور روایات کے علم بردار تھے۔ ان کی معروف تصانیف میں ذکر آثار الصّنادید، انتخاب خطوطِ غالبؔ، غالبؔ کا سفر کلکتہ اور ادبی معرکہ اور حسرت موہانی، مولوی عبدالحق۔ ادبی و لسانی خدمات وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ غالبؔ کے مکاتیب پر انھوں نے معیاری تحقیقی کام کیا۔ اس موضوع پر ان کی اوّلین کاوش ’’غالب کی نادر تحریریں ‘‘ تھی، اس کے بعد ’’غالب اور شاہان تیموریہ‘‘ اور’ ’ غالب کچھ مضامین‘‘ منظر عام پر آئیں۔ مکاتیبِ غالبؔ پر ڈاکٹر خلیق انجم کی قابل قدر تحقیق پانچ جلدوں پر مشتمل ہے۔
ڈاکٹر خلیق انجم ہندوستان کے شہر دہلی میں ضرور رہتے تھے لیکن وہ اصل میں اردو زبان و ادب کے سفیر تھے اور وہ جہاں بھی گئے اردو کی ترقّی، بقا اور فروغ کے لیے بات کی اور اس حوالے سے اپنا ہر ممکن کردار ادا کیا۔