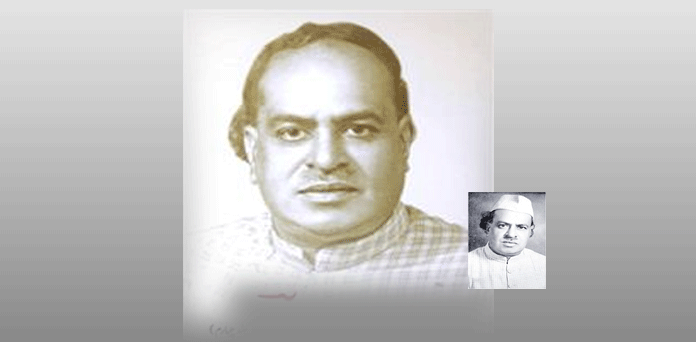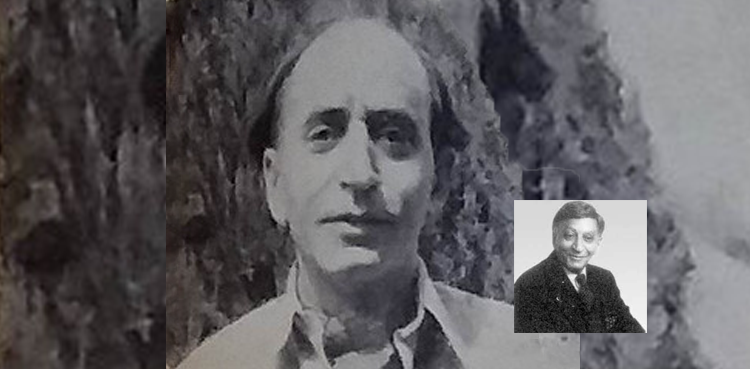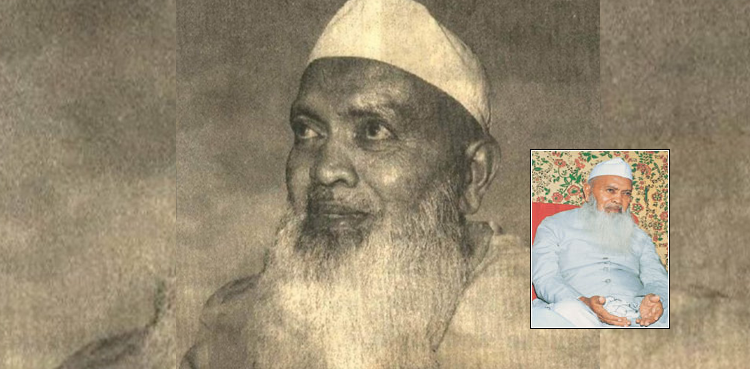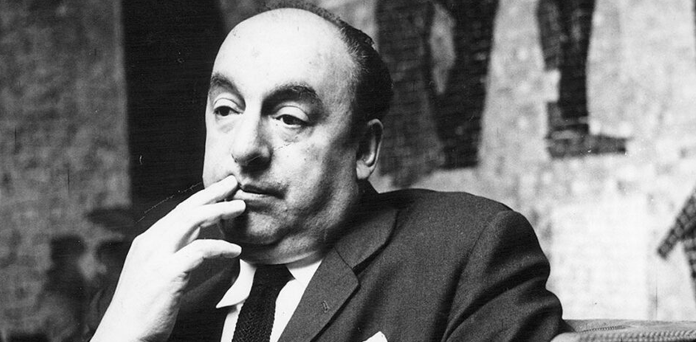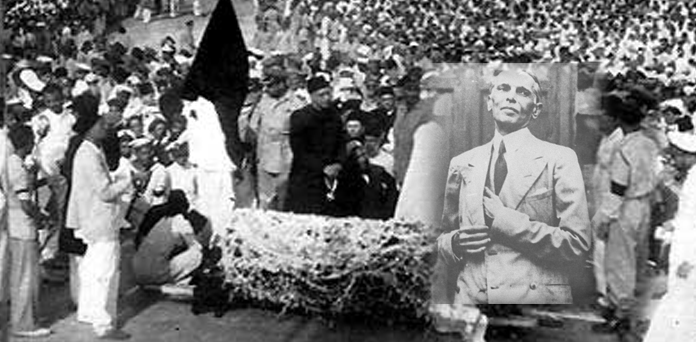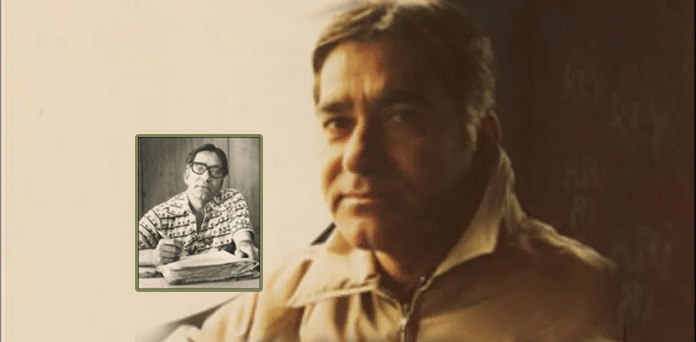11 ستمبر کو امریکا میں ٹوئن ٹاور پر دہشت گردوں کے حملوں کے بعد دنیا یکسر بدل گئی اور یہ تبدیلی سیاسی ہی نہیں تھی بلکہ اس نے مختلف اقوام اور معاشروں کو سماجی اور ثقافتی سطح پر بھی متاثر کیا۔ نائن الیون کے نام سے مشہور اس واقعے کے بعد امریکی اقدامات سے دنیا میں تشدد اور دہشت گردی کی جو لہر آئی، اس میں پاکستان کو جو نقصان اٹھانا پڑا اس کا اندازہ لگانا مشکل ہےاور ہمیں ایک ایسی جنگ میں دھکیل دیا گیا جس کا خمیازہ آج بھی بھگت رہے ہیں۔لیکن آج سے 76 سال قبل بھی قوم پر ایک سانحہ گزرا تھا جس نے ایک نئی مملکت کو ہلا کر رکھ دیا اور پاکستان اپنی بنیاد سے ہٹ گیا۔
ہم بات کر رہے ہیں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح ؒ کے سانحۂ ارتحال کی۔ آج قائداعظم کو 14 اگست کے بعد 25 دسمبر کو ان کے یوم ولادت اور 11 ستمبر کو یاد کیا جاتا ہے، ان کے مزار پر حاضری دی جاتی ہے۔ حکم راں اور قوم ان ایام میں قائداعظم کے افکار و کردار کو اپنے لیے مثالی قرار دے کر قیام پاکستان کے لیے ان کی جہدوجہد کی یاد تازہ کرتی ہے۔ سرکاری اور عوامی سطح پر منعقدہ تقاریب اور جلسوں میں ان کے طے کردہ اصولوں پر چلنے کے عزم کا اعادہ کیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد قائداعظم کی تصویر والے نوٹ ضرور ہمارے پاس ہوتے ہیں مگر ان کی ہدایات کو طاق نسیاں میں رکھ دیا جاتا ہے۔
قائد اعظم کی سربراہی میں اکابرین تحریک پاکستان کی مسلسل جدوجہد اور لاکھوں جانوں کی قربانیوں سے جب یہ وطن 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا تو مالی، انتظامی حوالے سے حالت انتہائی خستہ تھی اور اس کے مستقبل کے بارے میں دنیا شکوک و شبہات کا شکار تھی لیکن قائداعظم کی قیادت میں آزاد مملکت نے اپنی ترقی کا سفر شروع کیا جس کو صرف ایک سال بعد 11 ستمبر 1948 میں ایک زبرست دھچکا لگا اور پھر پاکستان کا جمہوری، نظریاتی بنیادوں پر ترقی معکوس کا سفر شروع ہوا اور آج 76 سال بعد قوم کئی نازک موڑ دیکھتے ہوئے ایسے چوراہے پر کھڑی ہے جہاں سے منزل کا نام ونشان نہیں مل رہا اور وہ مایوسی کے گہرے بادلوں میں ان راستوں کو دیکھ رہی ہے جن پر لسانیت، فرقہ واریت، دہشتگردی، عدم اعتماد اور کئی دیگر مسائل زہریلے ناگوں کی طرح پھن پھیلائے کھڑے ہیں اور آگے نہ جانے مزید کتنے نازک موڑ آنے ہیں اور یہ سب کسی اور کا نہیں بلکہ بحیثیت مجموعی قوم ہمارا ہی کیا دھرا ہے جو اب سامنے آ رہا ہے۔
قائد اعظم محمد علی جناح برصغیر پاک وہند کے مسلمانوں کو آزاد مسلم ریاست کا تحفہ دے کر اس کے قیام کے صرف ایک سال بعد 11 ستمبر 1948 کو ابدی نیند سو گئے۔ ان کی موت کی وجہ تپ دق (ٹی بی) بتایا جاتا ہے، جو اس دور میں ایک موذی مرض سمجھا جاتا تھا۔ تاہم جن حالات میں بانی پاکستان کی موت ہوئی اس سے جڑے سوالات آج بھی ذہنوں میں کلبلاتے ہیں اور پراسرار ہیں۔
ملک کا سربراہ جو اس نوزائیدہ مملکت کا بانی بھی ہو اور جس کو بالآتفاق بابائے قوم (یعنی قوم کا باپ) کا خطاب بھی دیا جا چکا ہو۔ اس کے آخری وقت میں جو کچھ ہوا وہ اب تک کئی بار مختلف مضامین میں ضبط تحریر میں لایا جا چکا ہے۔ کیسے انہوں نے جب اپنی زندگی کے آخری 60 ایام بلوچستان کے تفریحی مقام زیارت میں گزارنے کے بعد کراچی واپسی کا ارادہ کیا تو ان کا طیارہ تو کوئٹہ سے کراچی ماڑی پور ہوائی اڈے پر دو گھنٹے میں پہنچ گیا لیکن انہیں کراچی سے اپنی رہائشگاہ پہنچنے میں دو گھنٹے لگے۔
گورنر جنرل ہاؤس ماڑی پور سے 9 میل دور تھا۔ اس جاں بہ لب سربراہ مملکت جس کے پھیپھڑوں نے آخری درجے کی ٹی بی کے باعث کام کرنا چھوڑ دیا تھا اس کو لینے کے لیے ایسی کھٹارا ایمبولینس بھیجی گئی جو چار میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک جھٹکے کے ساتھ بند ہو گئی اور بتایا گیا کہ اس کا انجن خراب ہوگیا ہے اور یہ قافلہ ایک مرتے ہوئے انسان جو کوئی عام شخص نہیں بلکہ بانی پاکستان تھا کے ساتھ ایک گھنٹے سے زائد ماڑی پور کے جنگل میں بے بسی کے عالم میں کھڑا رہا۔ خدا خدا کر کے ایک دوسری ایمبولینس آئی تو یہ قافلہ اپنی منزل کی جانب روانہ ہوا۔ قائد اعظم کا قافلہ جس میں ان کی چھوٹی بہن فاطمہ جناح، ان کے ذاتی معالج اور عملہ شامل تھا گورنر جنرل ہاؤس پہنچا تو بانی پاکستان گہری نیند میں تھے لیکن ان کی طبیعت مسلسل بگڑ رہی تھی اور کچھ دیر میں ہی وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔
ڈاکٹر ریاض علی شاہ نے لکھا ہے کہ جناح کے آخری الفاظ ’اللہ۔۔۔ پاکستان‘ تھے جبکہ فاطمہ جناح’مائی برادر‘ میں لکھتی ہیں: ’جناح نے دو گھنٹے کی پرسکون اور بے خلل نیند کے بعد اپنی آنکھیں کھولیں، سر اور آنکھوں سے مجھے اپنے قریب بلایا اور میرے ساتھ بات کرنے کی آخری کوشش کی۔ ان کے لبوں سے سرگوشی کے عالم میں نکلا: فاطی۔۔۔ خدا حافظ۔۔۔ لاالٰہ الاللہ محمد الرسول اللہ۔‘ پھر ان کا سر دائیں جانب کو آہستگی سے ڈھلک گیا اور ان کی آنکھیں بند ہوگئیں۔
بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ چوہدری محمد حسین چٹھہ نے اپنے ایک انٹرویو میں ضمیر احمد منیر کو بتایا تھا کہ جب ڈاکٹر الٰہی بخش نے جناح کو بتایا کہ انھیں تب دق کا مرض لاحق ہے تو جناح نے جواب دیا: ’ڈاکٹر، یہ تو میں 12 برس سے جانتا ہوں، میں نے اپنے مرض کو صرف اس لیے ظاہر نہیں کیا تھا کہ ہندو میری موت کا انتظار نہ کرنے لگیں۔‘
برصغیر کی جدوجہد آزادی کے موضوع پر لکھی گئی مشہور کتاب ’فریڈم ایٹ مڈنائٹ‘ کے مصنّفین لیری کولنز اور ڈومینک لاپیئر نے بالکل درست لکھا ہے کہ: ’اگر اپریل 1947 میں ماؤنٹ بیٹن، جواہر لال نہرو یا مہاتما گاندھی میں سے کسی کو بھی اس غیر معمولی راز کا علم ہو جاتا جو بمبئی کے ایک مشہور طبیب ڈاکٹر جے اے ایل پٹیل کے دفاتر کی تجوری میں انتہائی حفاظت سے رکھا ہوا تھا، تو شاید ہندوستان کبھی تقسیم نہ ہوتا اور آج ایشیا کی تاریخ کا دھارا کسی اور رخ پر بہہ رہا ہوتا۔ یہ وہ راز تھا جس سے برطانوی سیکرٹ سروس بھی آشنا نہ تھی۔ یہ راز جناح کے پھیپھڑوں کی ایک ایکسرے فلم تھی، جس میں بانی پاکستان کے پھیپھڑوں پر ٹیبل ٹینس کی گیند کے برابر دو بڑے بڑے دھبے صاف نظر آ رہے تھے۔ ہر دھبے کے گرد ایک ہالا سا تھا جس سے یہ بالکل واضح ہو جاتا تھا کہ تپ دق کا مرض جناح کے پھیپھڑوں پر کس قدر جارحانہ انداز میں حملہ آور ہوچکا ہے۔‘
یہ وہ حقیقت ہے جس سے تقریباً ہر وہ پاکستانی جس نے تاریخ پاکستان اور قائداعظم کے آخری ایام کے حوالے سے معتبر کتب اور مضامین پڑھ رکھے ہیں، اچھی طرح واقف ہے، تاہم آج یہاں اس سب کو بیان کرنے کا مقصد نئی نسل کو باور کرانا ہے کہ قائداعظم ہمارے لیے خدا کا تحفہ تھے جن کی ایسی بے قدری کی کہ ان کا انتقال اس حال میں ہوا کہ جو کسی سربراہ مملکت بالخصوص کسی ملک کے بانی کے شایان شان قطعی نہیں تھا۔ شخصیت بھی وہ جنہوں نے اپنے جان لیوا مرض کی پروا نہ کرتے ہوئے کروڑوں مسلمانوں کے لیے ایک الگ خطہ وطن کی جدوجہد جاری رکھی۔ اگر وہ ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق اپنی مصروفیات ترک کر کے صحت پر توجہ دیتے تو اس صورت تحریک پاکستان کو زک پہنچنے کا امکان تھا اور یہ انہیں کسی صورت قبول نہ تھا۔ اس کو دوسرے معنوں میں کہہ سکتے ہیں کہ قائداعظم محمد علی جناح نے نئے وطن کے لیے اپنی زندگی کی قربانی دی اور اس بیماری کو دشمنوں سمیت دوست نما دشمنوں سے بھی چھپایا تاکہ ان کا مشن ناکام نہ ہوسکے۔ 1948 کے اس سانحہ نے پاکستان کو ہی پورا بدل دیا۔
قائداعظم کا خواب تھا کہ پاکستان ایک فلاحی، جمہوری ریاست ہو گی، جہاں پارلیمنٹ بالادست اور عوام کی حکمرانی ہوگی۔ جہاں ہر شخص کو بلاتفریق رنگ ونسل اور مذہب اس کے حقوق حاصل ہوں گے۔ اظہار رائے کی آزادی ہوگی اور صرف ادارے نہیں بلکہ ہر فرد قابل عزت ہوگا۔ اگر وہ اس طرح رخصت نہ ہوتے تو ملک کے آج حالات یہ نہ ہوتے۔ جس طرح نعمت خداوندی پر انعام ربانی بڑھتا ہے، اسی طرح اس کی عطا کردہ نعمت کی ناقدری پر اس کا حساب بھی اس قوم کو دینا پڑتا ہے۔ قائداعظم کے پاکستان اور ان کے فرمودات سے روگردانی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم 25 سال سے بھی کم عرصہ میں قائداعظم کا آدھا پاکستان گنوا بیٹھے اور جو باقی ماندہ پاکستان ہے وہاں کا جو حال ہے وہ آج سب کے سامنے ہے کہ جس کو عالم اسلام کی ترجمانی کرنی تھی، اس کے حکمران آج کاسہ گدائی اٹھائے پورے پروٹوکول اور شاہانہ انداز کے ساتھ نہ صرف آئی ایم ایف بلکہ ملک ملک پھر رہے ہیں۔ انا، مفادات، حرص و لالچ نے سب کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے جس کو قائد کے پاکستان کی بے بس عوام نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔