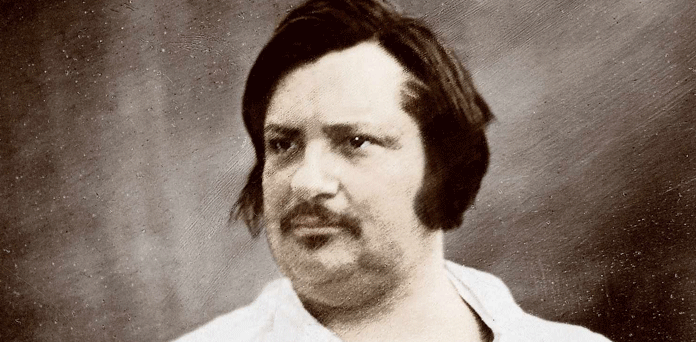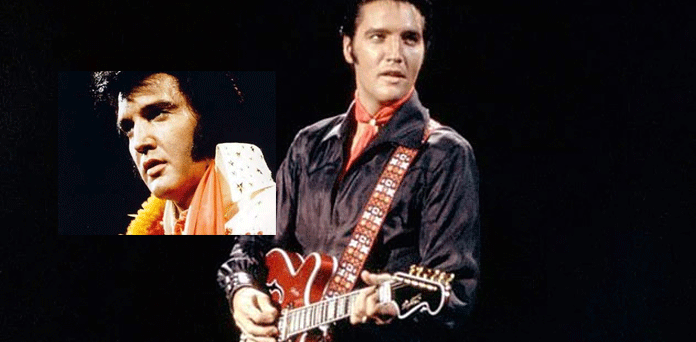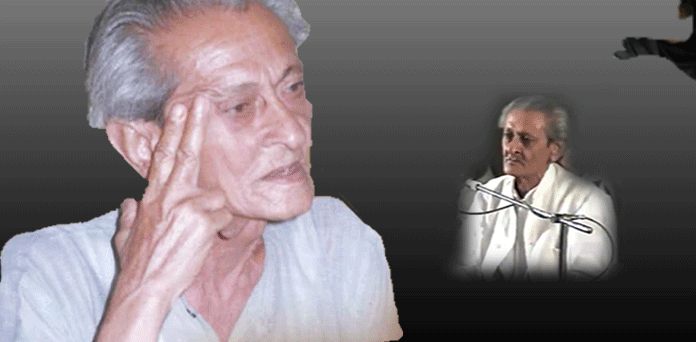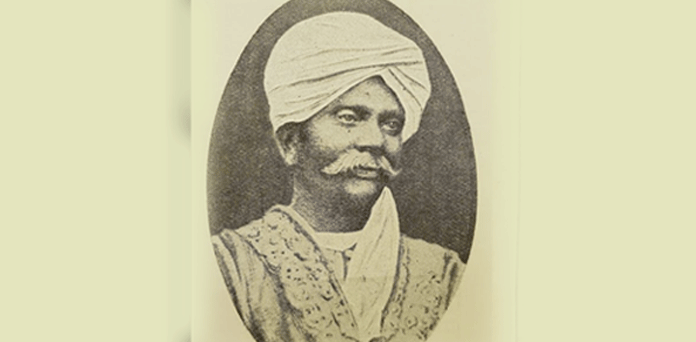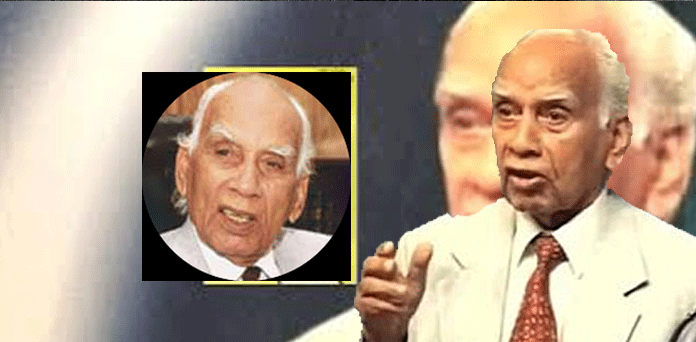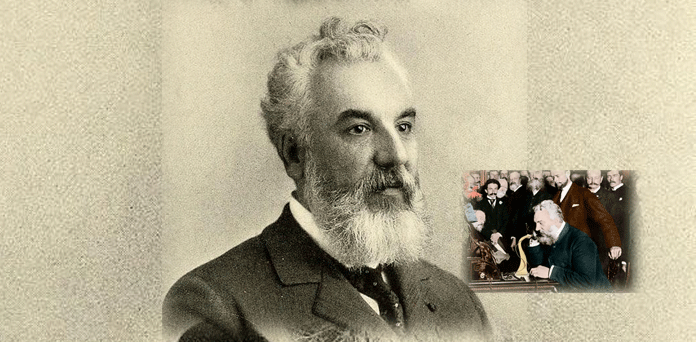بالزاک کو دنیا سے رخصت ہوئے ایک سو پچھتّر سال ہونے کو آئے ہیں، لیکن عالمی ادب میں اس کا نام آج بھی ایک حقیقت نگار کے طور پر زندہ ہے۔ ناول نگار اور مقبول ترین مختصر کہانیوں کے خالق بالزاک نے اپنی کہانیوں میں بیک وقت کئی کردار پیش کرکے انفرادیت کا ثبوت بھی دیا۔
بالزاک کو شروع ہی سے شہرت پسند تھی۔ وہ ایک ادیب کے طور پر ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا تھا۔ بالزاک کی یہ خواہش پوری ہوئی اور وہ فرانس کا مقبول ناول نگار بنا۔ بعد میں دنیا بھر میں اسے پذیرائی ملی اور آج بھی ناول نگاری میں اس کی انفرادیت کا چرچا ہوتا ہے۔ آج بالزاک کا یومِ وفات ہے۔ 1850ء میں بالزاک آج ہی کے دن چل بسا تھا۔
فرانسیسی ادیب بالزاک نے اپنی زندگی کے تجربات، سماجی رویّوں اور تبدیلیوں کا گہرا مشاہدہ کیا تھا۔ انہی تجربات اور مشاہدات نے بالزاک کو لکھنے پر آمادہ کیا اور وہ ایک حقیقت نگار کے طور پر سامنے آیا۔ اسے یورپی ادب میں حقیقت پسندی کو رواج دینے والا ناول نگار کہا جاتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر بالزاک کے زورِ قلم نے اپنے وقت کے مشاہیر کو بھی اپنی جانب متوجہ کیا جن میں چارلس ڈکنز، ایملی زولا، گستاف فلابیر، ہینری جیمس کے نام شامل ہیں۔ ان کے علاوہ عظیم فرانسیسی فلم ساز فرانسوا تروفو اور فلم ڈائریکٹر و ناقد ژاک ریوت بھی بالزاک سے بہت متأثر تھے۔ بالزاک کی تخلیقات کو فلمی پردے کے لیے ڈھالا گیا اور قارئین کے بعد بڑی تعداد میں فلم بین بھی اس سے متأثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔
ہنری ڈی بالزاک نے 1799ء میں پیرس کے قریب ایک گاؤں میں آنکھ کھولی۔ اس کا باپ سرکاری ملازم تھا۔ تعلیمی مدارج طے کرنے کے بعد بالزاک نے پیرس کا رخ کیا اور وہاں ایک وکیل کے ہاں بطور منشی ملازمت اختیار کرلی۔ بالزاک شروع ہی سے صحّت کے مسائل سے دوچار رہا اور ممکن ہے اسی باعث وہ حساس ہوگیا تھا اور مضطرب رہتا تھا۔ اپنے انہی جسمانی مسائل اور طبی پیچیدگیوں کے دوران وہ مطالعے کا عادی بن گیا اور پھر لکھنے کا آغاز کیا۔ بالزاک نے کہانیاں، ناول اور مختلف موضوعات پر مضامین بھی سپردِ قلم کیے جنھیں بے حد سراہا گیا۔
وکیل کے پاس اپنی ملازمت کے دوران بالزاک مسلسل لکھتا رہا۔ معاش کی فکر اور روزگار کی تلاش اسے پبلشنگ اور پرنٹنگ کے کام کی طرف بھی لے گئی، لیکن مالی آسودگی بالزاک کا مقدر نہیں بنی۔ تب، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ قلم کی مزدوری کرے گا اور نام و مقام بنائے گا۔ اس نے یہی کیا اور قسمت نے بالزاک کا ساتھ نبھایا۔
یہاں ہم بالزاک کے تخلیقی سفر سے متعلق ایک نہایت دل چسپ واقعہ نقل کررہے ہیں جو مختلف ادبی تذکروں میں پڑھنے کو ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بالزاک کی بہن کی شادی تھی اور ایک روز جب تمام رشتے دار گھر میں موجود تھے، بالزاک نے ان کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی اور اپنا لکھا ہوا پہلا ڈرامہ پڑھ کر سنانے لگا۔ پورا ڈرامہ سنانے کے بعد بالزاک نے جب داد طلب نظروں سے حاضرین کی طرف دیکھا تو سب نے یک زبان ہوکر کہا، "یہ بالکل بکواس ہے۔” لیکن نوجوان بالزاک نے ان کے اس تبصرے کو اہمیت نہ دی اور لکھنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ پھر وہ دن دن بھی آیا جب فرانس اور بعد میں بالزاک کو دنیا بھر میں ایک ناول نگار اور ڈرامہ نویس کے طور پر شہرت ملی۔
اس فرانسیسی مصنّف کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ہمیشہ ایک نوٹ بک اور پنسل اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ وہ فرانس کی تاریخ، اور مقامی سطح پر ہونے والی ہر قسم کی اہم سماجی اور ثقافتی تبدیلیوں کو قلم بند کرنا چاہتا تھا اور جہاں بھی جاتا، بالخصوص فرانس کے مختلف علاقوں کے کوچہ و بازار، محلّوں اور شہروں کی سڑکوں کی تفصیل نوٹ کرتا رہتا تھا، فرصت ملنے پر وہ ان مشاہدات کے مطابق کردار اور ان پر کہانیاں تخلیق کرتا۔ وہ اکثر سڑکوں اور میدانوں میں درختوں اور کیاریوں کا جائے وقوع لکھ لیتا تھا اور اپنے ناول یا ڈرامے میں انہی درختوں کے درمیان اپنے کردار دکھاتا جس سے وہ حقیقت سے قریب تر معلوم ہوتیں۔
بالزاک نے ٹھان لی تھی کہ ہر سال کم از کم دو ضخیم ناول، درجنوں کہانیاں اور ڈرامے ضرور لکھے گا اور اس نے یہ کیا بھی۔ فرانس کے مصنّف نے کئی شاہکار کہانیاں تخلیق کیں، اور 97 ناول لکھے۔ بوڑھا گوریو بالزاک کا وہ مقبول ناول ہے جس کا اردو زبان میں بھی ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ اسی طرح یوجین گرینڈ بھی فرانس میں محبّت کی ایک لازوال داستان ہے جس میں ایک لڑکی اپنے کزن کی محبّت میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ ہنری ڈی بالزاک نے یہ ناول انقلابِ فرانس کے بعد اس معاشرے میں جنم لینے والے نئے رحجانات کے پس منظر میں تخلیق کیا ہے۔ ”تاریک راہوں کے مسافر“ میں بالزاک کی کردار نگاری عروج پر ہے جب کہ جزئیات نگاری کی وجہ سے بھی اسے بہت سراہا جاتا ہے۔
فرانسیسی ادیب بالزاک کے طرزِ نگارش کا ایک وصف طویل فقرے ہیں اور اس کے بیان کردہ منظر میں بہت تفصیل موجود ہوتی ہے۔ بالزاک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شروع ہی سے انفرادیت کا قائل تھا اور اپنے احباب سے کہتا تھا کہ میں قلم سے وہ کام لوں گا کہ لوگ مجھے فراموش نہیں کرسکیں گے۔ بلاشبہ بالزاک نے اپنے زورِ قلم کو منوایا اور فرانسیسی معاشرے کا گویا پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دیا۔ اس تخلیق کردہ کردار آج بھی فرانس ہی نہیں ہمارے معاشرے میں بھی دیکھے جاسکتے ہیں۔
بالزاک کا ایک ادبی کارنامہ اور وجہِ شہرت وہ تخلیقات ہیں جو بعنوان ہیومن کامیڈین شایع ہوئیں۔ اس میں بالزاک نے فرانس کے ہر شعبہ ہائے حیات اور ہر مقام سے کردار منتخب کرکے کہانیاں تخلیق کیں، اس کے ناول فرانس میں تہذیبی اور ثقافتی تاریخ کے ساتھ انفرادی آداب، عادات، لوگوں کے رجحانات، ان کی رسومات اور جذبات کی مؤثر ترجمانی کرتے ہیں۔
بالزاک کے بارے میں اوپر بیان کیا گیا ہے کہ وہ طبی مسائل اور کئی پیچیدگیوں میں مبتلا ہو گیا تھا اور غالباً اسی سبب وہ حساس طبع ہونے کے علاوہ کچھ شخصی کم زوریوں اور تضادات کا شکار بھی رہا۔ یہ کم زرویاں اس کی وہ خامیاں بن گئیں جن کی وجہ سے اکثر اسے ناپسند کیا جاتا تھا۔ عقیل احمد روبی اس حوالے سے لکھتے ہیں: لین دین کے سلسلے میں بالزاک بڑا ناقابل اعتماد آدمی تھا۔ اس کا بائیو گرافر آندرے بلی کہتا ہے کہ بالزاک شرمناک حد تک واہیات نادہندہ تھا۔ بہنوں، دوستوں، واقف کاروں، پبلشروں کے ساتھ اس نے کبھی کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کیا حتیٰ کہ اس نے اس سلسلے میں اپنی ماں تک کو ناکوں چنے چبوا دیے۔آندرے بلی نے بالزاک کے نام اس کی ماں کا ایک خط بالزاک کی بائیو گرافی میں دیا ہے۔ چند جملے دیکھیے۔’’تمہارا آخری خط مجھے نومبر 1834ء میں ملا تھا۔ جس میں تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم اپریل 1835ء سے مجھے ہر تین ماہ کے بعد دو سو فرانک خرچہ دیا کرو گے۔ اب اپریل 1837ء آ گیا ہے تم نے مجھے ایک فرانک تک نہیں بھیجا۔ بالزاک تم سوچ نہیں سکتے یہ وقت میں نے کیسے گزارا ہے۔ اب وقت آگیا ہے کہ میں دونوں ہاتھ پھیلا کر کہوں ’’خدارا مجھے روٹی دو‘‘۔ اب تک میں جو کچھ کھاتی رہی وہ میرے داماد نے مجھے دیا۔ یہ کب تک چلے گا۔ میرے بچے تم فرنیچر پر، لباس پر، جیولری پر اور عیاشی پر خرچہ کرتے ہو اپنی ماں کے بارے میں بھی سوچو۔‘‘بالزاک نے خط پڑھ کر ماں کو اس خط کا جواب دیا جو ایک جملے پر مبنی تھا اور وہ جملہ یہ تھا۔’’میرا خیال ہے تم پیرس آ کر مجھ سے ایک گھنٹہ بات کرو۔‘‘