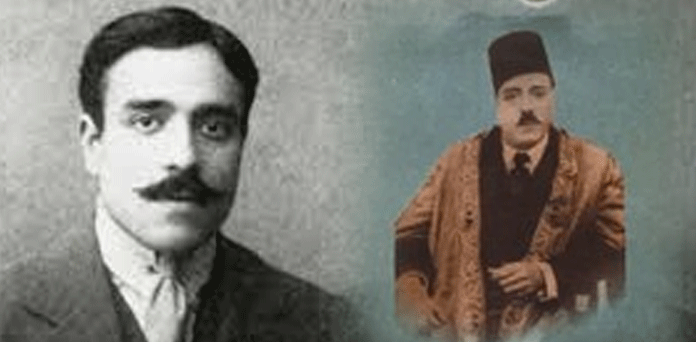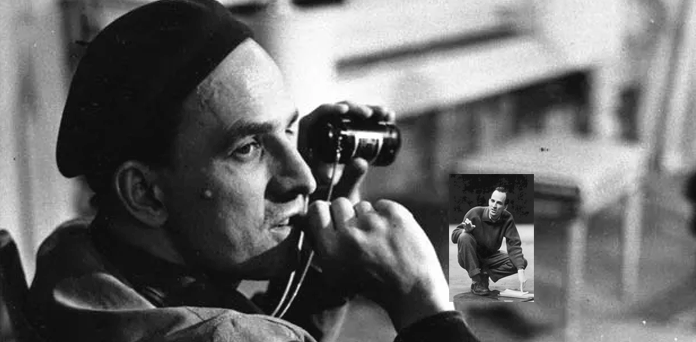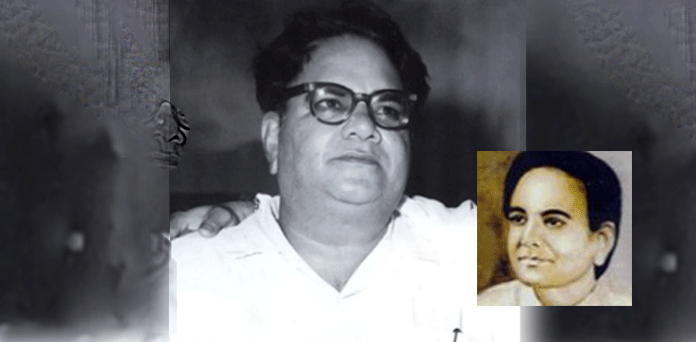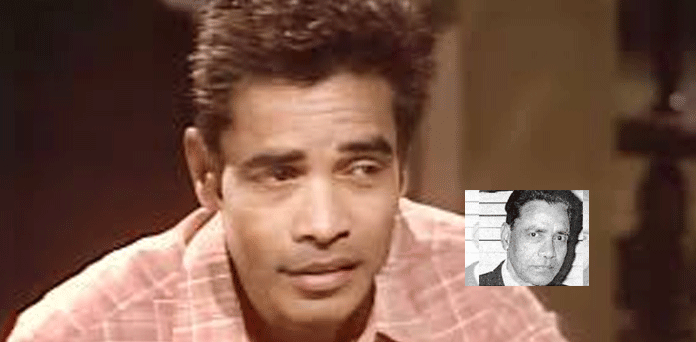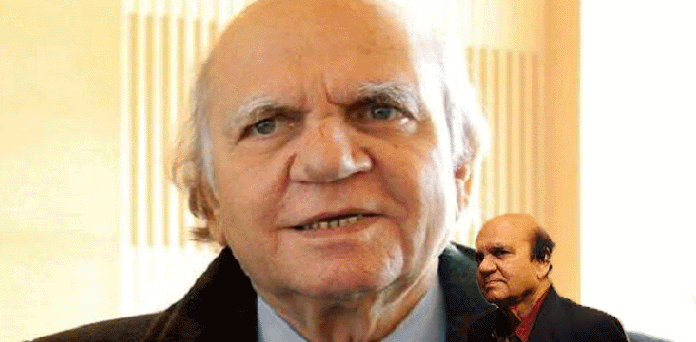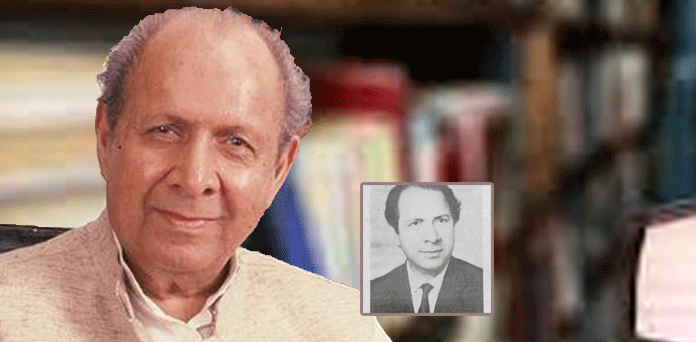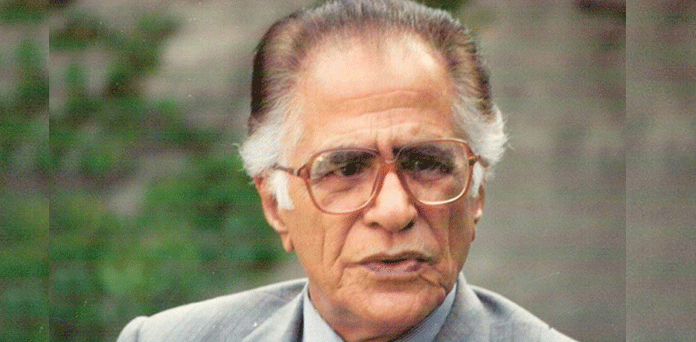ہندوستان میں اردو ادب، ترقی پسند تحریک کا عروج، پھر تقسیمِ ہند سے قبل انقلاب کی گونج میں جن اہلِ قلم نے شہرت اور نام و مقام پایا، علی سردار جعفری انہی میں سے ایک ہیں۔
علی سردار جعفری ترقی پسند تحریک کے پلیٹ فارم سے اپنے افکار و نظریات کی ترویج و تبلیغ تمام عمر کرتے رہے اور اپنی تخلیقات کے ذریعے عالمی امن، ہندوستان میں بھائی چارے اور عالمی سطح پر انسان دوستی کا پرچار کیا۔ وہ فرد کی آزادی اور ترقی و خوش حالی کے لیے نظمیں لکھتے رہے اور ہر خاص و عام نے ان کے کلام کو سراہا۔ آج علی سردار جعفری کا یومِ وفات ہے۔
یہ بھی پڑھیے: اختر الایمان جنھیں سردار جعفری کی انانیت نے پنپنے نہ دیا!
انقلاب آفریں نغمات کے خالق علی سردار جعفری نے اپنے تخلیقی وفور اور قلم کے زور پر ملک گیر شہرت اور مقبولیت حاصل کی اور اس دور کے نئے قلم کاروں کو متاثر کیا۔ وہ شاعر، نقّاد اور ایسے مضمون نگار تھے جن کے قلم سے کئی توصیفی اور تنقیدی مضامین، افسانے اور ڈرامے ہی نہیں نکلے بلکہ انھوں نے اپنی یادداشتوں اور ادبی تذکروں پر مبنی تحریریں بھی یادگار چھوڑی ہیں۔
بنیادی طور پر علی سردار جعفری نظم کے شاعر تھے لیکن انھوں نے غزلیں بھی کہی ہیں اور گیت نگاری بھی کی جن میں خاص طور پر ایک جذباتی رو پائی جاتی ہے۔ ان کے کلام ایک ایسا صوتی آہنگ ہے جو اپنی مثال آپ ہے۔ علی سردار جعفری درد مند اور انسان دوست مشہور تھے اور ان اہلِ قلم میں سے ایک تھے جنھوں نے قوم اور فرد کی آزادی اور ترقی کا خواب دیکھا اور عوام کے جذبات کی ترجمانی کی۔
علی سردار جعفری بلرام پور (ضلع گونڈہ، اودھ) میں 29 نومبر 1913ء کو پیدا ہوئے اور یکم اگست 2000ء کو ممبئی میں انتقال کیا۔
ممتاز شاعر علی سردار جعفری نے ایک انٹرویو میں اپنے حالاتِ زندگی، تعلیم و تربیت اور اپنے ادبی سفر کا احوال یوں بتایا تھا: میرا نام اس اعتبار سے غیر معمولی ہے کہ آج تک اس نام کا دوسرا آدمی نہیں ملا۔ ہاں سردار علی نام کسی قدر عام ہے۔ حافظ شیرازی کے ایک قصیدے میں علی سردار اس طرح استعمال ہوا ہے کہ میرے نام کا سجع بن جاتا ہے۔
انھوں نے اپنی تعلیم اور مشاغل و معمولاتِ نوعمری سے متعلق بتایا، سب سے پہلے گھر پر بہار کے ایک مولوی صاحب نے اردو، فارسی اور قرآن کی تعلیم دی۔ وہ رات کو قصص الانبیاء سناتے تھے۔ اس کے بعد دینی تعلیم کے لیے سلطان المدارس لکھنؤ بھیج دیا گیا، وہاں جی نہیں لگا۔ ایک مولوی صاحب کے گھر قیام تھا۔ وہاں بھی جی نہیں لگا اور میں فرار ہو کر بلرام پور واپس چلا گیا۔ بلرام پور کے انگریزی اسکول لائل کالجیٹ ہائی اسکول میں داخلہ لیا۔ کھلی فضا تھی، اچھے استاد تھے، ہم عمر لڑکوں سے دوستیاں تھیں۔ صبح ناشتہ کر کے گھر سے اسکول جانا اور شام کو چار بجے پھر واپس آکر ناشتہ کرنا، اور میل ڈیڑھ میل دور ایک پریڈ گراؤنڈ میں پیدل جا کر دو گھنٹے کرکٹ، ہاکی کھیلنا روز کا معمول تھا۔
علی سردار جعفری کے مطابق، اسی زمانے میں انیسؔ کے زیرِ اثر شاعر شروع کی۔ 1933ء میں بیس سال کی عمر میں ہائی اسکول کی تعلیم مکمل کر کے علی گڑھ مسلم یونی ورسٹی میں داخلہ لیا۔ (ابتدائی تعلیم کے چند سال ضائع ہوگئے تھے)
یہ ایک طوفانی زمانہ تھا جب تحریکِ آزادی اپنے شباپ پر تھی۔ اس عہد کے علی گڑھ نے اردو زبان کو اختر حسین رائے پوری، سبط حسن، منٹو، مجاز، جاں نثار اختر، جذبی، خواجہ احمد عباس، جلیل قدوائی، اختر انصاری، شکیل بدایونی، عصمت چغتائی اور 1940ء کے آس پاس اخترالایمان کا تحفہ دیا۔ وہاں خواجہ منظور حسین، ڈاکٹر عبدالعلیم، ڈاکٹر رشید جہاں، ڈاکٹر محمد اشرف وغیرہ سے تعارف ہوا اور جن کی صحبت اور فیض نے ذوقِ ادب اور آزادی کے جذبے کو جلا عطا کی۔
ایک ہڑتال میں حصہ لینے کی وجہ سے مسلم یونیورسٹی کو خیر باد کہنا پڑا اور دہلی جا کر اینگلو عربک کالج میں داخلہ لیا۔ یہ وہ تاریخی کالج تھا جو دہلی کالج کے نام سے ایک بڑا تعلیمی کردار ادا کرچکا تھا۔ وہاں داخلہ دلوانے میں جلیل قدوائی اور اختر انصاری نے مدد کی۔ اس واقعہ کے پچاس سال بعد 1986ء میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے ڈی لٹ (D.Litt.) کی اعزازی ڈگری سے عزت افزائی کی۔ یہ میرے لیے اس اعتبار سے بہت بڑا اعزاز تھا کہ مجھ سے پہلے اعزازی ڈگری شعراء کی فہرست میں علامہ اقبال، مسز سروجنی نائیڈو اور حضرت جگر مراد آبادی کو عطا کی گئی تھی۔
وقت گزرا تو جہاں انھوں نے اپنی شاعری کے ذریعے مقام بنایا اور ترقی پسند دانش ور اور مصنّف کے طور پر مشہور ہوئے، وہیں آزادی کے لیے ان کی سیاسی جدوجہد کا زمانہ بھی یہی تھا اور علی سردار جعفری کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے متحرک اور فعال رکن بھی بن چکے تھے۔ وہ لکھتے ہیں، جواہر لال نہرو سے اسی زمانے میں ملاقات ہوئی اور ملاقات کا یہ شرف آخر دن تک قائم رہا۔ ان کے انتقال سے دو ماہ قبل تین مورتی ہاؤس میں اندرا گاندھی نے ایک چھوٹا سا مشاعرہ پنڈت جی کی تفریح طبع کے لیے کیا تھا، جس میں فراقؔ، سکندر علی وجدؔ اور مخدوم محی الدّین بھی شامل تھے۔ میں نے اپنی نظم “میرا سفر” فرمائش پر سنائی تھی۔
علی سردار جعفری کا تعلمی سفر درجہ بہ درجہ جاری تھا اور اسی دوران وہ شاعری اور کمیونسٹ پارٹی کے بینر تلے اپنی سیاسی اور سماجی سرگرمیوں میں بھی مگن تھے، وہ اس بارے میں وہ لکھتے ہیں، دہلی سے بی۔ اے کرنے کے بعد میں لکھنؤ آ گیا۔ پہلے مجازؔ کے ساتھ قانون کی تعلیم کے لیے ایل۔ ایل۔ بی میں داخلہ لیا۔ ایک سال بعد اس کو چھوڑ کر انگریزی ادب کی تعلیم کے لیے ایم۔ اے میں داخلہ لیا۔ لیکن آخری سال کے امتحان سے پہلے جنگ کی مخالفت اور انقلابی شاعری کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا اور لکھنؤ ڈسٹرکٹ جیل اور بنارس سنٹرل جیل میں تقریباً آٹھ ماہ قید رہا اور پھر بلرام پور اپنے وطن میں نظر بند کر دیا گیا۔ یہ نظر بندی دسمبر 1941ء میں ختم ہوئی۔
لکھنؤ میں سجاد ظہیر، ڈاکٹر احمد وغیرہ کی صحبت رہی۔ وہیں پہلی بار ڈاکٹر ملک راج آنند سے ملاقات ہوئی۔ 1938ء میں کلکتہ میں ترقی پسند مصنفین کی دوسری کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس موقع پر شانتی نکیتن جا کر ٹیگور سے ملاقات کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ وہیں بلراج ساہنی سے ملاقات ہوئی جو ہندی پڑھاتے تھے۔
1943ء میں بمبئی آنا ہوا۔ سجاد ظہیر کے ساتھ کمیونسٹ پارٹی کے ہفتہ وار اخبار ’قومی جنگ‘ میں صحافتی فرائض انجام دیتا رہا۔ اس محفل میں بعد کو سبط حسن، مجازؔ، کیفیؔ، محمد مہدیؔ وغیرہ شامل ہوئے۔ آہستہ آہستہ بمبئی اردو ادب کا مرکز بن گیا۔ 1949ء کے بعد بمبئی میں جوشؔ، ساغر نظامی، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، میرا جی، اخترالایمان، سجاد ظہیر، ساحرؔ، کیفیؔ، مجروحؔ، حمید اختر اور بہت سارے سربرآوردہ ادیب جمع ہوگئے۔ اس زمانے کی انجمن ترقی پسند مصنفین کے ادبی اجلاس نے پوری اردو دنیا میں ایک دھوم مچا رکھی تھی۔ باہر سے آنے والے ادیب ان اجلاسوں میں بڑی مسرت سے شریک ہوتے تھے۔
1949ء میں جو ہندوستانی سیاست کا ہیجانی دور تھا اور کمیونسٹ پارٹی کی انتہا پسندی اپنے شباب پر تھی، حکومت ہند کی طرف سے پارٹی پر پابندی عاید کر دی گئی۔ پورے ملک میں بڑے پیمانے پر گرفتاریاں شروع ہوئیں۔ میں بمبئی میں دو بار گرفتار کیا گیا۔ پہلی بار پندرہ دن کے لیے۔ دوسری بار ڈیڑھ سال کے لیے۔ یہ زمانہ بمبئی کے آرتھر روڈ جیل اور ناسک کی سنٹرل جیل میں گزرا۔ 1950ء میں یکایک رہا کر دیا گیا۔ وہ عید کی شام تھی۔ دوسرے دن صبح ہی صبح بمبئی آ کر گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ عید کا دن تھا۔
ان کے تحریر کردہ ڈرامے اور افسانے بھی مختلف ادبی پرچوں کی زینت بنتے تھے جب کہ ممبئ سے چھپنے والا سہ ماہی "نیا ادب” ان کے زیرِ ادارت شایع ہوتا تھا۔ علی سردار جعفری ایک بہترین مترجم بھی تھے اور شیکسپئر کی چند تحریروں کے علاوہ دوسرے قلم کاروں کی تخلیقات کے تراجم بھی کیے۔ علی سردار جعفری کی ادبی تخلیقات پر مشتمل کتابوں میں ان کی نظموں کے مجموعہ پرواز (1943)، نئی دنیا کو سلام (طویل تمثیلی نظم، 1948)، امن کا ستارہ (دو طویل نظمیں 1950ء)، ایک مجموعہ پتھر کی دیوار (1953ء) اور لہو پکارتا ہے (1968ء) میں شایع ہوئے جب کہ افسانوں کی کتاب منزل (1938ء)، ڈراموں کا مجموعہ یہ خون کس کا ہے (1943ء) شایع ہوئی۔ اس کے علاوہ کتاب بعنوان لکھنؤ کی پانچ راتیں (1965ء)، اقبال شناسی (1969ء) میں منظر عام پر آئی۔ انھوں نے فلمی گیت بھی لکھے اور فلم کی دنیا میں بطور مصنّف بھی جگہ بنائی۔
بھارت میں علی سردار جعفری کی ادبی خدمات کو سراہتے ہوئے پدم شری ایوارڈ جب کہ حکومت پاکستان کی جانب سے 1978ء میں اقبال میڈل (تمغائے امتیاز) دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ علی سردار جعفری کو خصوصی تمغائے ماسکو (ستّر سالہ جشنِ پیدائش پر) 1984ء میں عطا کیا گیا تھا۔ 1997ء میں بھارت نے انھیں گیان پیٹھ ایوارڈ بھی دیا تھا۔