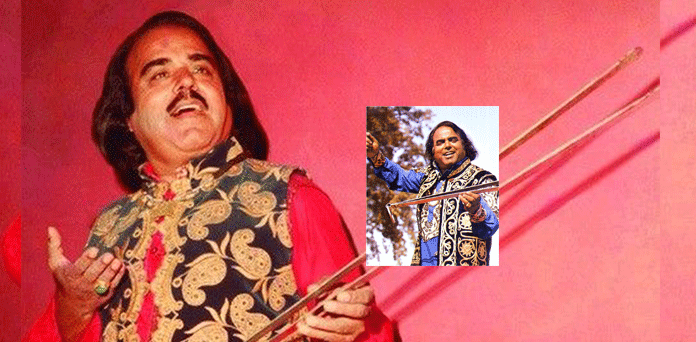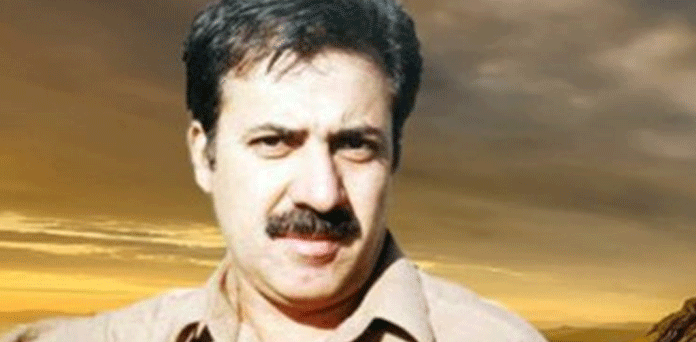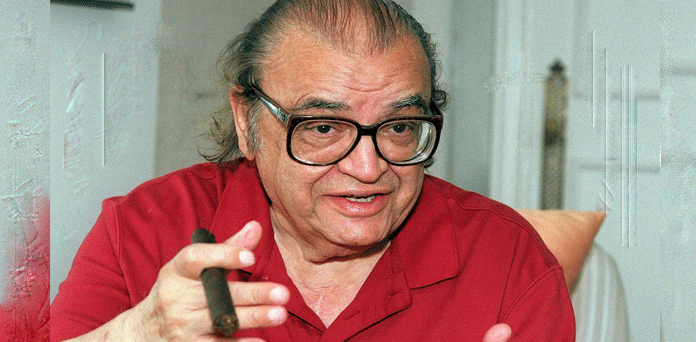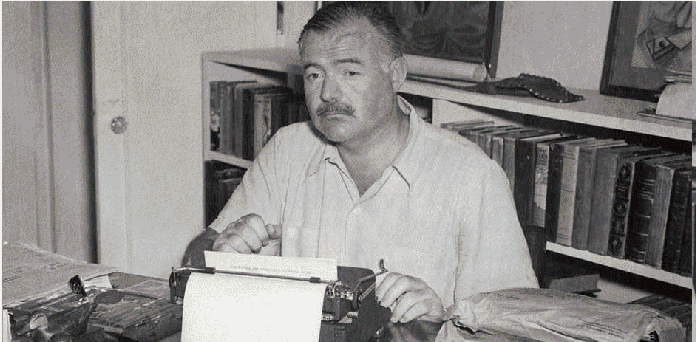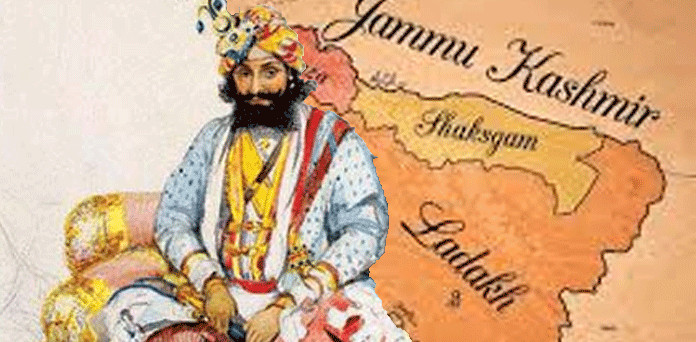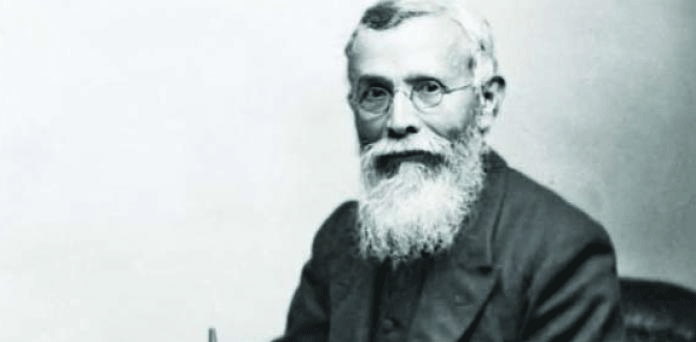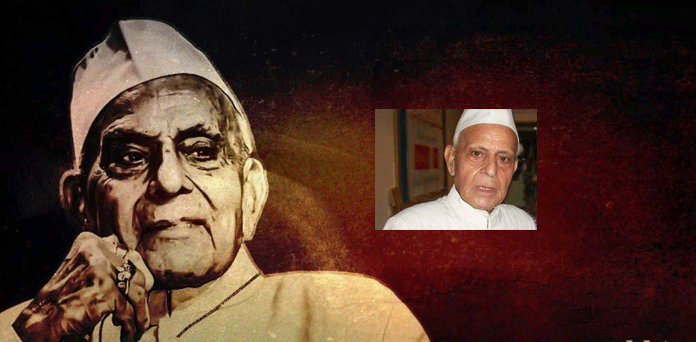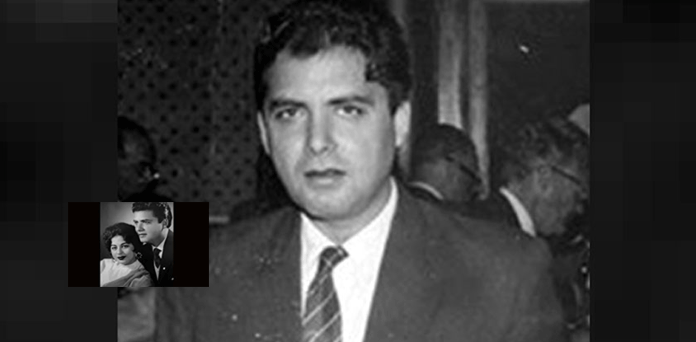برصغیر پاک و ہند میں لوک موسیقی اور مقامی سازوں کے ساتھ اپنے فن کا جادو جگا کر یہاں مقبول ہونے والے فن کاروں میں کئی ایسے بھی ہیں جنھیں ان کے فن کی بدولت دنیا بھر میں شہرت ملی اور انھوں نے بیرونِ ملک اپنے ملک کا نام بھی روشن کیا۔ عالم لوہار انہی میں سے ایک ہیں، لیکن ان کی پہچان ایک ایسے بانکے سجیلے فن کار کے طور پر بنی جس نے چمٹے کو بطور ساز استعمال کرتے ہوئے اپنی خداداد صلاحیتوں اور ہنر کو آزمایا اور شہرت پائی۔
عالم لوہار کی انفرادیت ان کی خاص ثقافتی پہچان کے ساتھ ان کے ہاتھوں میں سُر بکھیرتا اور نغمگی کا احساس دلاتا ایک چمٹا تھا جس کے ذریعے انھوں نے بڑی مہارت سے موسیقی بکھیری۔ وہ پاکستان کے ایسے لوک فن کار تھے جن کا تعلق پنجاب کی دھرتی سے تھا۔ پنجاب جو کئی لوک داستانوں اور اپنی ثفاقت کی وجہ سے مشہور ہے، اس مٹی پر جنم لینے والے عالم لوہار کی آواز میں بہت سے گیت امر ہوگئے۔ مارچ 1928ء میں گجرات میں پیدا ہونے والے عالم لوہار کو قصہ خوانی اور داستان گوئی میں کمال حاصل تھا۔ ناقدینِ فن کہتے ہیں کہ عالم لوہار نے لوک داستانوں کو اس دردمندی، ذوق و شوق اور سچائی کے ساتھ گایا کہ سننے والوں کے دلوں میں اترتی گئیں۔ انھوں نے جو گیت گائے ان میں پیار محبت کا درس اور نصیحت ملتی ہے اور ان کی آواز میں لوک موسیقی ایک خوب صورت پیغام بن کر سماعتوں کو معطر کرتی ہے۔
عالم لوہار بچپن ہی سے خوش الحان تھے اور شروع ہی سے گانے کا شوق تھا۔ پنجاب کا خاص کلچر ہمیشہ سے موضوعِ بحث رہا ہے جس میں بیٹھکوں اور نجی محافل میں قصّے کہانیاں، حکایات، گیت اور کافیاں سن کر لوگ اپنا دل بہلاتے تھے۔ عالم لوہار اپنی منفرد آواز میں لوک داستانوں کو لے اور تال کے ساتھ انہی بیٹھکوں میں دوسروں کو سنایا کرتے تھے۔ یہ اس دور میں لوگوں کی تفریحِ طبع کا بہترین ذریعہ تھا جب کہ میلے ٹھیلے، اکھاڑے اور تھیٹر بھی اس دور میں بہت مقبول تھے۔ عالم لوہار نے اپنے علاقہ کے لوگوں کو اپنا مداح بنا لیا تھا اور پھر وہ میلے ٹھیلوں اور تھیٹر کے لیے بھی پرفارم کرنے لگے۔ اس وقت ان کے ہم عصروں میں عنایت حسین بھٹی، بالی جٹی، طفیل نیازی، عاشق جٹ اور حامد علی بیلا وغیرہ کے تھیڑ پنجاب کے طول و عرض میں خاصی شہرت رکھتے تھے اور لوگ ان کو بہت شوق سے سنتے تھے۔ عالم لوہار نے داستان امیر حمزہ، مرزا صاحباں، داستانِ ہیر رانجھا اور سسی پنوں کے علاوہ جگنی اور مختلف گیت بھی گائے جن میں سے کچھ پنجابی فلموں کا بھی حصہ بنے تاہم ان کی گائی ہوئی جگنی ان کی وجہِ شناخت بنی اور اسے ہر جگہ سراہا گیا۔ عالم لوہار کے فرزند عارف لوہار نے بھی اسی فن کو اپنایا اور شہرت حاصل کی۔
عالم لوہار کے ایک ساتھی فضل کریم قسائی ان کا ساتھ نبھاتے تھے اور وہ الغوزہ بجاتے تھے۔ عالم لوہار اور ان کا ساتھ ہمیشہ قائم رہا۔ عالم لوہار نے زندگی کے آخری ایام میں وطن تھیٹر کے ساتھ زیادہ کام کیا اور پرفارمنس سے لوک موسیقی کے دیوانوں کو محظوظ کرتے رہے۔ عالم لوہار اکثر اپنے گیتوں کی دھنیں بھی خود ہی بناتے تھے۔ ان کا معروف گیت ’’واجاں ماریاں بلایا کئی وار میں، کسے نے میری گل نہ سنی‘‘ انہی کا لکھا ہوا تھا اور اس کی دھن بھی عالم لوہار نے بنائی تھی۔ ان کی آواز میں ’’دل والا روگ نئیں کسے نوں سنائی دا، اپنیاں سوچا وچ آپ مر جائی دا‘‘ نے بھی مقبولیت حاصل کی۔ عارفانہ کلام میں ’’ساری رات تڑف دیا لنگھ جاندی، درداں دے مارے نئی سونداے، جیڑی رات نوں سوہنا چن نہ چڑھے، اس رات نوں تارے نئی سوندے‘‘ نے عالم لوہار کو بہت شہرت دی۔
گلوکار عالم لوہار کی شناخت ان کے شانوں تک لٹکے بال، اور کڑھائی والے کرتے ہوا کرتے تھے جس میں ان کی چھب ہی نرالی ہوتی۔ اس کے ساتھ چمٹا جسے انھوں نے بطور ساز استعمال کیا کچھ اس خوبصورتی سے ان کی شان بڑھاتا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔
عالم لوہار 3 جولائی 1979ء کو مانگا منڈی کے قریب ٹریفک حادثے میں خالقِ حقیقی سے جا ملے۔ پنجاب کا یہ عظیم لوک فن کار لالہ موسیٰ میں ابدی نیند سو رہا ہے۔ عالم لوہار کو حکومتِ پاکستان نے بعد از مرگ صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا تھا۔