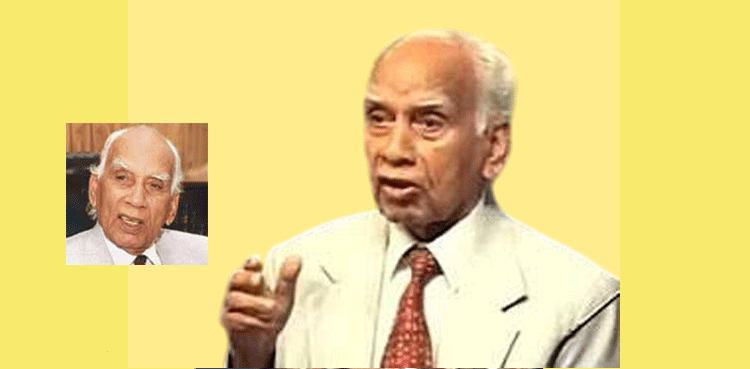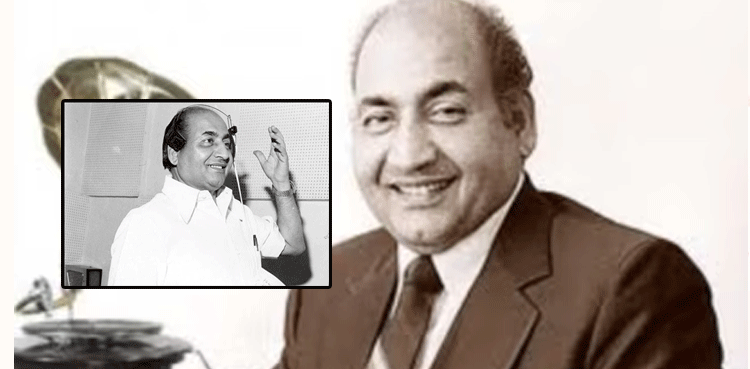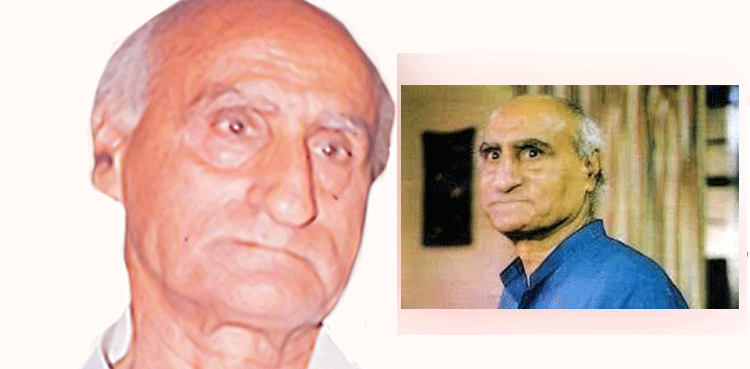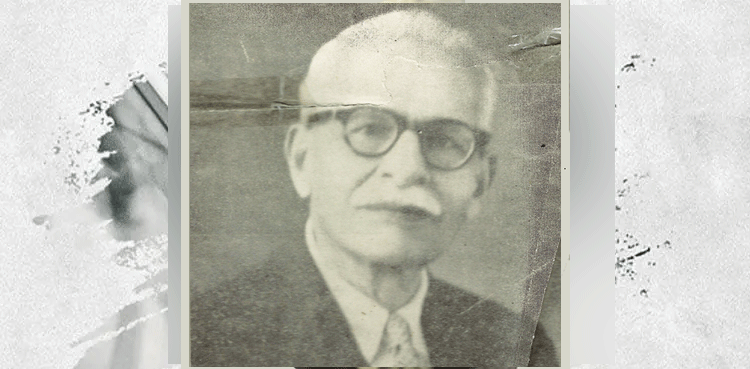پاکستانی فلم انڈسٹری میں شمیم آرا کو ان کے فن اور پروقار شخصیت کی بدولت مقبولیت ہی نہیں بے پناہ عزت اور احترام بھی ملا۔ وہ اپنے وقت کی مقبول ترین فلمی ہیروئن تھیں جن کا کیریئر 30 سال پر محیط ہے۔ آج شمیم آرا کی برسی منائی جارہی ہے۔
اداکارہ شمیم آرا نے ہیروئن کے بعد بطور کریکٹر ایکٹریس بھی بڑی شان سے اپنی فن کارانہ صلاحیتوں کا اظہار کیا۔ انھوں نے بعد میں بطور ہدایت کار بھی خود کو منوایا تھا۔
شمیم آرا کا تعلق بھارت کے شہر علی گڑھ سے تھا جو ایک علمی و تہذیبی مرکز رہا ہے۔ وہ علی گڑھ سے پاکستان منتقل ہوگئی تھیں۔ شمیم آرا کا اصل نام ’’پتلی بائی‘‘ تھا جنھیں پاکستانی فلموں میں فلم ساز و ہدایت کار نجم نقوی نے شمیم آرا کے نام سے متعارف کروایا۔ وہ اردو فلم’’ کنواری بیوہ‘‘ میں پہلی مرتبہ بطور اداکار نظر آئیں جو ایک ناکام فلم ثابت ہوئی مگر شمیم آرا نے اپنی ابتدائی دور کی ناکامیوں کے باوجود انڈسٹری سے تعلق برقرار رکھا اور پھر وہ لاہور چلی گئیں۔ شمیم آرا کو لاہور میں نام ور ہدایت کار ہمایوں مرزا نے اپنی فلم ’’ہم راز‘‘ میں اداکارہ مسرت نذیر کے ساتھ کاسٹ کیا اور سائیڈ رول شمیم آرا نے بھرپور پرفارمنس سے فلم بینوں کو اپنی جانب متوجہ کرلیا۔ فلم سازوں کو اداکارہ کے مکالمے ادا کرنے کا سادہ انداز اور بہترین اردو کا تلفظ اچھا لگا اور رفتہ رفتہ شمیم آرا کے فن و شخصیت میں نکھار آتا گیا۔
اداکارہ کو اصل شہرت اردو زبان میں میں بننے والی فلم ’’بھابی‘‘ سے ملی۔ اس کے بعد ’’سہیلی‘‘ اور ’’فرنگی‘‘ وہ فلمیں ثابت ہوئیں جنھوں نے شمیم آرا کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ اردو فلم ’’لاکھوں میں ایک‘‘ میں شمیم آرا کی پرفارمنس بہت جاندار رہی اور اس فلم نے شان دار کامیابی حاصل کی۔ اس فلم کے بعد شمیم آرا فلم انڈسٹری کی مصروف ترین اداکار بن گئیں۔ شمیم آرا نے مشہور رنگین فلم ’’نائلہ‘‘ میں اپنے وقت کے مقبول ہیرو اور باکمال اداکار سنتوش کمار کے ساتھ مرکزی کردار ادا کیا۔ ان کی جوڑی بہت پسند کی گئی۔بعد میں شمیم آرا نے کمال، محمد علی، ندیم اور وحید مراد کے ساتھ بھی کام کرکے فلم بینوں کے دل جیتے۔ شمیم آرا کو فلموں میں مختلف نوعیت کے کردار ادا کرنے کا بے حد شوق تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ شمیم آرا نے اداکاری کے ساتھ بطور ہدایت کار اور فلم ساز بھی کام کیا۔
اداکارہ شمیم آرا کی ذاتی زندگی میں کئی پریشان کن موڑ آئے۔ ان کی کوئی شادی بھی کام یاب نہ ہوسکی۔ اس وقت اداکار کمال اور شمیم آرا کے درمیان محبت اور شادی کا چرچا بھی ہوا۔ لیکن شمیم آرا کی نانی کی وجہ سے بات آگے نہ بڑھ سکی۔ شمیم آرا کی شادی فلم ساز فرید احمد سے ہوئی جنھوں نے ’عندلیب‘، ’بندگی‘، ’سہاگ‘، ’خواب اور زندگی‘ اور ’زیب انسا‘ جیسی کام یاب فلمیں بنائیں۔ پھر شمیم آرا فلم ساز و تقسیم کار اے مجید کی دلہن بنیں۔ آخری شادی تقریباً بڑھاپے میں دبیرالحسن نامی فلمی رائٹر سے کی تھی۔ جب شمیم آرا کا فلم انڈسٹری میں وقت ختم ہوا تو دبیر الحسن نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور تب وہ اپنے بیٹے کے پاس لندن چلی گئیں۔ لندن ہی میں 5 اگست 2016ء کو وفات پائی اور وہیں آسودۂ خاک ہوئیں۔
فلم کی دنیا میں شمیم آرا نے ’ہمراز، سہیلی، دوراہا، صاعقہ، مجبور، زمانہ کیا کہے گا، سہاگ، فرنگی، چنگاری، سالگرہ سمیت 86 فلموں میں اداکاری کی۔ ان کی مشہور فلموں میں قیدی، اک تیرا سہارا، انسان بدلتا ہے، آنچل، لاکھوں میں ایک، دل بیتاب، خاک اور خون، پرائی آگ، دوسری ماں، فیصلہ، بھابھی، پلے بوائے شامل ہیں۔
شمیم آرا انتہائی خوش اخلاق اور مؤدب خاتون مشہور تھیں اور ساتھی فن کاروں کے مطابق انھیں بہت کم غصہ آتا تھا۔ شمیم آرا انتہائی حساس طبیعت کی مالک تھیں۔ ابتدائی عمر میں ہی ماں کی شفقت سے محروم ہوگئی تھیں اور نانی کے زیر تربیت رہیں جن کے فیصلوں کے آگے وہ بے بس تھیں۔ شمیم آرا کی پیشہ ورانہ زندگی پر ان کی نانی کی گرفت سخت رہی۔ اداکارہ کی پیدائش 1940ء کی تھی۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد پاکستان کے شہر کراچی آگئی تھیں اور یہاں سے لاہور منتقل ہوگئیں جو فلمی مرکز بنا ہوا تھا۔
اداکارہ کو 1960ء میں صدارتی ایوارڈ دیا گیا تھا جب کہ بہترین نگار ایوارڈ فلم ’’فرنگی پر ملا تھا۔ شمیم آرا کو اس لیے بھی یاد کیا جاتا ہے کہ انھوں نے اپنی فلموں میں عورت کو طاقت ور اور بہادر دکھایا ہے جس کی مثال ’مس ہانگ کانگ‘، ’مس کولمبو‘، ’مس سنگاپور‘ اور ’مس بینکاک‘ جیسی فلمیں ہیں جن میں ہیروئن اور خاتون کردار کو انھوں نے ظالم اور بدمعاش سے لڑتے ہوئے پیش کیا۔