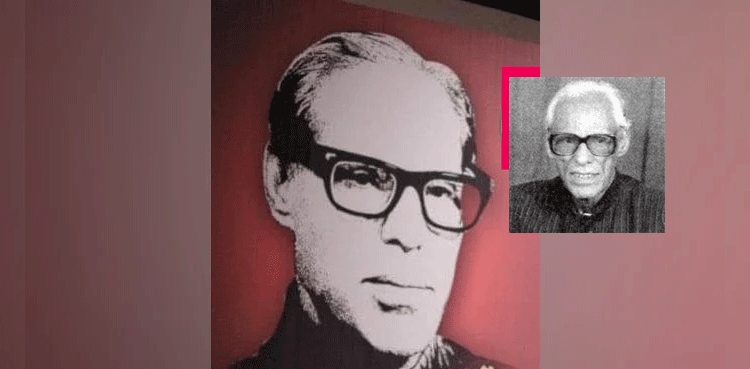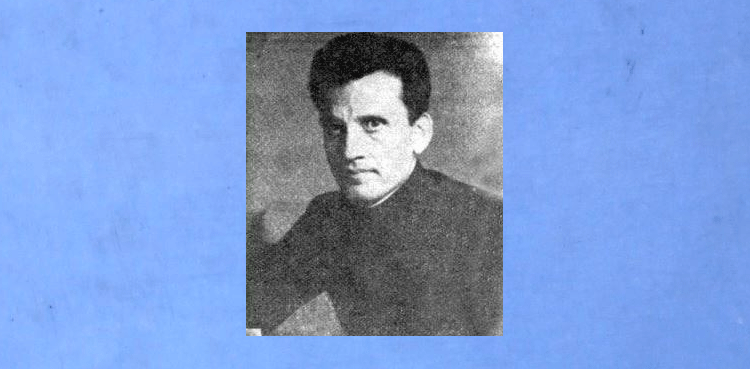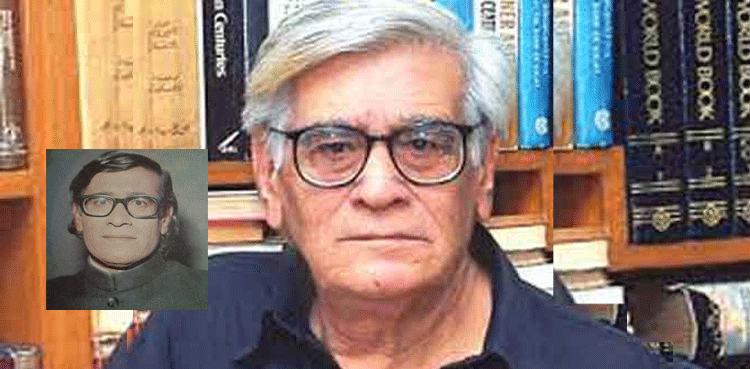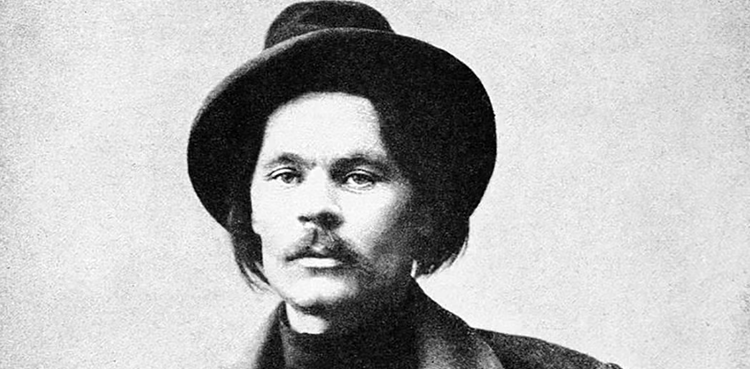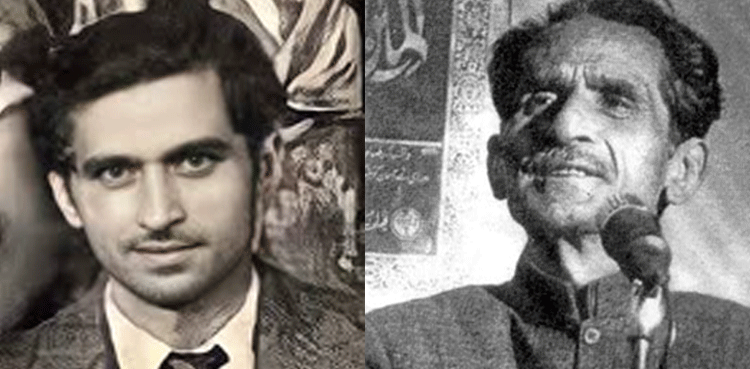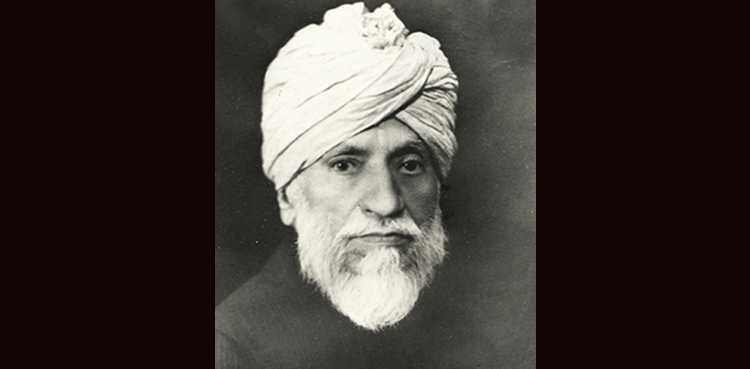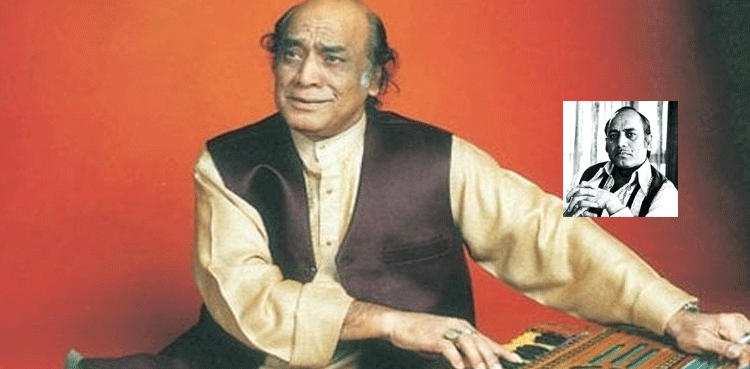اردو میں افسانہ نگاری کے اوّلین دور میں اعظم کُریوی نے اپنی کہانیوں اور قدیم ہندی شاعری کے اردو تراجم کے سبب شہرت پائی۔ وہ پریم چند جیسے ممتاز فکشن نگار کے دبستان سے تعلق رکھتے تھے۔ اعظم کریوی نے ہندوستانی معاشرت اور لوگوں کے اخلاق و حالت پر مبنی کہانیاں لکھیں جو بے حد مقبول ہوئیں۔ ان کی کہانیوں میں کوئی الجھاؤ اور پیچیدگی نظر نہیں آتی بلکہ یہ سلاست کے ساتھ نتیجہ خیز افسانے ہیں جو انھیں ایک کام یاب افسانہ نگار بناتی ہیں۔ اعظم کُریوی کو کراچی میں قتل کر دیا گیا تھا۔
اعظم کریوی 1899ء کو متحدہ ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ آبائی وطن کُرئی ہے اور اسی مناسبت سے کُریوی اپنے قلمی نام سے جوڑا۔ افسانہ نگار کا اصل نام انصار احمد تھا۔ انھوں نے تقسیم سے قبل بطور کلرک سرکاری ملازمت اختیار کی اور اسی زمانہ میں بطور افسانہ نگار اور مترجم بھی شہرت پانے لگے۔ اُن کی تخلیقی صلاحیت پہلے پہل شعر گوئی کے روپ میں ظاہر ہوئی۔ بعد میں نثر کو اپنایا، ان کی تحریریں زمانہ، نگار، عصمت، مخزن اور ہمایوں جیسے مشہور و معروف رسائل میں شایع ہوئیں۔ یہی افسانے اور تراجم کتابی شکل میں بھی بہم ہوئے۔ اعظم کریوی نے کئی شہروں میں بسلسلۂ ملازمت قیام کیا اور بعد میں پاکستان میں بھی سرکاری محکمے سے وابستہ رہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد مختلف اداروں سے وابستہ ہوئے۔
22 جون 1955ء کو اعظم کریوی اپنی سائیکل پر ڈرگ روڈ اسٹیشن کے قریب سے گزر رہے تھے کہ ان کے قتل کا افسوس ناک واقعہ پیش آیا۔ پولیس کا خیال تھا کہ کسی لٹیرے نے ان سے لوٹ مار کے دوران مزاحمت پر انھیں قتل کیا ہے۔ اعظم کریوی ڈرگ روڈ کے علاقہ میں ہی سکونت پذیر تھے اور اپنے گھر لوٹ رہے تھے۔ ڈاکٹر اعظم کریوی کے افسانوی مجموعوں میں شیخ و برہمن، انقلاب، پریم کی چوڑیاں، دکھ سکھ، کنول اور دکھیا کی آپ بیتی سرفہرست ہیں۔ یہاں اس معروف افسانہ نگار کی ایک تخلیق نقل کررہے ہیں جس کا عنوان فٹ پاتھ ہے۔
یہ فٹ پاتھ پر زندگی گزارنے والے ایسے بچے کی کہانی ہے، جو ایک امیر شخص کے گھر پر اوپری کام کاج کے لیے نوکر ہونے پہنچتا ہے۔ وہ اسے نئے کپڑے دیتا ہے اور ایک کمبل بھی تھماتا ہے۔ مگر بچہ کمبل لینے سے انکار کر دیتا ہے۔ بچہ اپنے مالک سے کہتا ہے کہ وہ فٹ پاتھ پر اپنے ٹھکانے سے جاکر اپنی چادر لانا چاہتا ہے۔ مالک سے اجازت لے کر یہ بچہ گھر سے نکلتا ہے اور پھر لوٹ کر نہیں آتا۔ کہانی ملاحظہ کیجیے۔
شہر میں سڑکوں کی دونوں طرف کی دنیا ہر جگہ یکساں نہیں ہوتی۔ کہیں بھرے بازار کے درمیان سڑک یوں نرمی سے بل کھاتی ہوئی گزرتی ہے جیسے مشتاقوں کے ہجوم میں حسن سر محفل۔ آمدورفت کی کثرت سے کھوئے سے کھوئے چھلتے ہیں۔ کہیں شاندار رہائشی محلوں سے اس کا گزر ہوتا ہے۔ دو طرفہ نئی وضع کی کوٹھیاں، سبزہ زار احاطے، دھنک کی طرح رنگ برنکی ہنستی ہوئی کیاریاں، جدید فیشن کے لباس، ناز فرماتی ہوئی ساریاں، نغمہ زن بالا خانے اوردھومیں مچاتی ہوئی موٹریں اور کہیں مفلوک الحال حلقوں کا جگر چیرتی ہوئی یہ سڑکیں یوں تیر جاتی ہیں جیسے اپی ہوئی تلوار۔
بڑی سڑکوں کے حاشیوں پر فٹ پاتھ کا وجود ان کے وقار میں اضافہ کرتا ہے۔ سڑکوں کی بہ نسبت فٹ پاتھ کی دنیا ذرا آہستہ خرام کرتی ہے۔ سڑک ندی کے درمیانی دھارے کی طرح ہوتی ہے اور فٹ پاتھ موج ساحل آشنا کی مثال۔ مگر فٹ پاتھ کی دنیا حرکت و سکون دونوں کے مناظر پیش کرتی ہے۔ لہٰذا زیادہ دلچسپ ہے۔ رہررؤں کے علاوہ فٹ پاتھ کی آغوش میں بہت سی ہستیاں ہوتی ہیں۔ جمادات، نباتات، حیوانات اور اشرف المخلوقات بھی، جی ہاں اشرف المخلوقات بھی جس پر حوریں رشک کریں اور جن کے سامنے فرشتے سجدے میں گریں۔
میونسپلٹی کے ٹین اپنی الا بلا، کوڑے کرکٹ، بہارن کے ساتھ ایسے دکانداروں کے پلنگ جو صرف نفع کمانا، قانون کو دھوکا دینا اور ساری دنیا کو اپنا سمجھنا جانتے ہیں۔ صرف پلنگ ہی نہیں، بنچ، کرسیاں، ٹوکرے، دیودار کے بکس وغیرہ وغیرہ۔ ہندوستانی وزیروں کی طرح موٹے تازے، ہچکتے دمکتے مگر مجبور و پا بہ گل لیٹر بکس اور حیوانات میں بکریاں، گائیں گھوڑے، گدھے، کتے اور سب کے سبھاپتی سانڈ دوسروں کی کمائی کھانا خود بیکار رہنا اور دندنانا۔ ویسے ساہو کاروں، کارخانہ داروں اور زمینداروں کی طرح، سانڈ بھی کچھ نہ کچھ کام کرتے ہی رہتے ہیں۔ نباتات میں میوے کی بڑی دکانوں سے پھیکے ہوئے چھلکے اور ایسی ٹوکریوں کے بیر، خراب و خستہ کے لیے اور آدھی سڑی ہوئی نارنگیاں جن کی پوری کائنات ایک گوشے میں سما جاتی ہے۔ غرض یہی ہستیاں فٹ پاتھ کی رونق ہوتی ہیں۔ مگر جو اشرف المخلوقات نہ ہوتا تو آسمان و زمین، جمادات، نباتات و حیوانات کہاں ہوتے۔ فٹ پاتھ پر اشرف المخلوقات بھی ہوتے ہیں۔ مسلسل سدا لگائے ہوئے فقیر، اپاہج بھک منگے، بھنکتے ہوئے کوڑھی جو اپنے ٹھنٹہ ہاتھوں کو دکھا کر صرف سوالیہ اشارے کرتے ہیں۔ ایسے زار و نزار محتاج جو برائے نام سا چیتھڑا سامنے بچھاکر بے حس و حرکت لیٹے رہتے ہیں۔ نصف درجن سے زیادہ گندے اور ادھ موئے بچوں والی عورت جو بیر یا شکر قند، رکشا والوں اور قلیوں کے ہاتھ بیچتی ہیں۔ ایک پلہ نما بچہ ربود کُرتی سے ڈھکی، ڈھلکی ہوئی خشک چھاتیوں کو اس طرح چاٹتا ہوا جیسے کوئی غریب جو آم کے پھینکے ہوئے چھلکوں کو رس گل جانے کے بعد بھی چاٹ لینا پسند کرے۔ میلے برقعے کے اندر سے نکیاتی ہوئی سائلہ عورت۔ چائے کی پھینکی ہوئی سیٹھی سے بننے والی چائے بیچنے والے اور ان کے گرد بیکار اور تھکے ہوئے مزدور اور راتوں کو انہیں فٹ پاتھوں کے سینوں کی دبی ہوئی آگ دہک اٹھتی ہے۔ خالی خولی ہانڈیوں میں چند دانے ابلتے ہیں۔ پانی کے ابال کی آواز دھرتی کی کراہ معلوم ہوتی ہے۔ بھوکے پیٹوں کو جگا کر فٹ پاتھ پر زندگی بسر کرنے والے سونے کی نقل کرنے کے لیے زمین پر دراز ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح زندگی کا چکر چلتا رہتا ہے اور قسمت کے بہانے برداشت کر لیا جاتا ہے۔
آج میں آپ کو فٹ پاتھ ہی سے متعلق ایک کہانی سنانے والا ہوں۔ نہ جانے کتنی بن کہی اور ان سنی کہانیاں فٹ پاتھوں سے گرد راہ کی طرح لپٹی ہوئی ہوں گی۔
دس سال کی عمر کا ایک لڑکا میرے مکان کے سامنے سڑک کے چھوٹے سے پل پر بیٹھا ہوا تھا۔ پاؤں پھیلائے ہوئے، بے پروا آزاد، کمر میں لنگوٹی کسی بے شرم کی یونہی سی لاج کی طرح چپکی ہوئی۔ گردن سے ایک میلا، ڈھیلا، ڈھالا، چور چور کسی کا اتارن کرتہ جھول رہا تھا۔ شکستہ کرتے کے چاکوں کو ایک حد تک چھپانے میں سیاہ مرزئی مدد دے رہی تھی، جو خود بھی اکثر جگہ خندۂ دنداں نما کی شکل پیدا کر رہی تھی۔ یہ مرزئی بھی یوں تھی جیسے چھوٹے تکیے کا خول پہنا دے۔ کرتا جانگھ تک آتا تھا اور سامنے پھٹے ہونے کے سبب جسم زیریں کی عریانی کو دور کرنے کی بجائے، اس کے ننگے ہونے کا پردہ فاش کر رہا تھا اور اس کے بال الجھے ہوئے تھے اور اس کے سیاہ ہاتھ پاؤں پر گرد کی تہیں نمایاں طور پر جمی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ زمین کی خاک اور جسم کے پسینے نے مل کر یہ ابٹنا تیار کیا تھا۔ وہ شاید بہت دیر سے بیٹھا ہوا تھا۔ سہ پہر کی دھوپ نے جا بجا پسینہ چلا کر ابٹنے کو ہلکا کر دیا تھا۔ سر کے بال پسینے میں چپک رہے تھے۔ وہ سنہری دھوپ سے لطف اٹھا رہا تھا۔ دنیا سے لاپروا ہو کر وہ اپنی مرزئی کے اوپر کی چلٹیریں مار رہا تھا اور گاہ گاہ اپنا بدن تیزی سے کھجا لیا کرتا تھا۔
میرا محلہ شہر کا ایک خاموش حصہ تھا۔ دو جانب کالج کے کوارٹر تھے، تیسری جانب دریا اور چوتھے جانب درمیانی اور ادنیٰ طبقے کے لوگوں کے کچھ مکانات، وہ نجانے ادھر کیسے آ نکلا۔ شاید پکنک کے لیے روزمرہ کے ہنگاموں سے تنگ آکر محض یونہی آج اس کی ٹانگیں ادھر ہی اسے لے آئیں۔ جاڑے کے دن تھے۔ دسمبر کا مہینہ اسے دھوپ میں بڑے اطمینان و سکون سے بیٹھا دیکھ کر یہ اثر ہوتا تھا جیسے کوئی بچہ ماں کی گود میں عالم رنج و حسرت کو بھول کر آسودگی و طمانیت کے ساتھ بیٹھا ہوا ابدیت کے ساتھ رشتہ جوڑ رہا ہو۔
میرا ملازم اسے بلا کر میرے مکان کے اندر لے آیا۔ پہلے تو اس نے پکار تک نہ سنی۔ وہ اتنا محو تھا۔ شور کرنے سے وہ چونکا، مگر شان سے پل ہی پر بیٹھا رہا۔ جب اسے اندر بلایا گیا تو اس نے بہت ہی مشکوک تیور سے ماحول کو بھانپا اور پھر چپلٹیریں مارنے لگا۔ خوشامدیں کرنے، چمکارنے اور دلاسے دینے پر مشکلوں سے وہ کشاں کشاں یوں اندر لایا گیا جیسے چھتر کے میلے سے ایک نئے اڑتے ہوئے گریزاں بچھڑے خرید کر کوئی کسان ڈراتا ہوا لیے جا رہے ہو۔
شاید وہ کچھ بہرا بھی تھا اور اس کی دونوں آنکھوں میں پھولیاں تھیں۔ ایک میں زیادہ، دوسری میں کم۔ وہ گھر کی چار دیواری کے اندر گھبرایا گھبرایا سا معلوم ہو رہا تھا۔ نو گرفتار پرندے کی طرح، سائبان سے دوڑ کر وہ انگنائی میں چلا گیا اور کنوئیں کی منڈیر پر لاپروائی سے بیٹھ گیا۔ گردن نیچی کئے ہوئے وہ شرما کر دانت نکالے آہستہ آہستہ ہنس رہا تھا۔ اس کے دانت پیلے پیلے تھے۔ پھسی سے اٹے ہوئے جیسے دانتوں پر سونا چڑھایا جاتا ہے۔ ہم لوگوں نے اسے کھانا دیا۔ وہ بہ مشکل کھانے پر راضی ہوا مگر جب کھانے لگا تو بھوکے کتے کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ صحن میں بیٹھا بیٹھا جب وہ رکابی صاف کر چکا تو تیزی سے گرسنہ بھڑیے کی طرح وہ باورچی خانے میں گھس گیا اور کھانے کی مزید چیزیں تلاش کرنے لگا۔ قاب، ہانڈیاں، پیالے، ٹکریاں سب اس نے الٹ پلٹ کرنی شروع کیں، باورچی نے اسے ڈانٹ بتائی، ہم لوگوں نے اسے سمجھایا کہ یہ بدتمیزی ہے اور کھانا ہو تو مانگ کر کھایا کرو۔ مگر یہ باتیں اس کی سمجھ سے باہر تھیں۔ وہ اس وقت تک بے چین رہا جب تک اسے کچھ اور کھانے کو نہ مل گیا۔
دوبارہ کھا کر بھی اس کے تقاضے جاری رہے۔ ہم لوگوں نے اسے سمجھایا کہ اب رات کو کھانا پیٹ بھر پھر ملے گا۔ وہ کچھ مایوسی اور جھلاہٹ کے عالم میں رکابی سے دال اور شوربا چاٹنے لگا۔ چاٹ واٹ کر رکابی کو ایک طرف نہایت ہی بے توجہی سے سرکا دیا اور کنوئیں کی منڈیر پر جا کر بیٹھ گیا۔ بےتعلق سا، بے حس، بے فکر، وہ بہت ہی کم باتوں کا جواب دیتا تھا۔ ہم لوگوں کو گملوں اور چمن کی آبپاشی کے لیے ایک ایسے چھوکرے کی ضرورت تھی جو اوپر کے اور کام بھی کر دیا کرے، اس لونڈے کو ہم نے خداداد سمجھا۔ کم دانے گھاس میں یہ بہت سے کام کر دیتا۔ خود غرضی اور جذبۂ ترحم نے مل کر ہم میں یہ شدید خواہش پیدا کی کہ کسی طرح یہ باد آورد ہمارے ہاں ٹک جائے۔ ہم لوگوں نے اسے سمجھانا شروع کیا کہ وہ نوکر ہو کر یہاں اگر رہ جائے تو اسے خوب کھانے کو ملے گا، اچھے صاف صاف کپڑے پہننے کو ملیں گے اور پیسے بھی۔ وہ چپ سنتا رہا۔ کبھی کبھار اپنے پیلے پیلے دانت نکال کر ہنس دیتا۔ عجیب طرح کی بے تعلق، بے جذبے کی کھوکھلی سی ہنسی۔ ہم لوگوں نے اسے نہانے کو کہا، وہ فوراً تیار ہو گیا۔ اسے نہانے کو کپڑا دھونے والا صابن دیا گیا۔ اس نے اسے سونگھا اور منہ بنا لیا۔ پھر ہنستا ہوا نہانے کے لیے کل پر بیٹھ گیا۔ اسے ایک پرانا ہاف پینٹ اور ایک پرانی قمیص دی گئی۔ اس نے خوش خوش انہیں پہنا۔ بٹن لگاتے وقت اسے بڑا لطف آ رہا تھا۔ کئی بار بٹن کھول کھول کر انہیں لگائے۔ وہ جدت کا لطف لے رہا تھا۔ اپنے کرتے اور مرزئی میں اس قسم کی نامعقول بندشیں نہیں تھیں۔ نہا دھو کپڑے بدل کر وہ سیدھا باورچی خانے میں گھس گیا اور اب کے اس نے باورچی سے بہ منت کچھ اور کھانے کو مانگا۔ چند سوکھی روٹیاں اسے دے دی گئیں اور اس نے انہیں ہفتوں کے بھوکے کی طرح دو تین لقموں میں ختم کر دیا۔ کھا کر وہ اٹھا اور اپنے پھٹے پرانے کرتے میلی چکٹ لنگوٹی اور چیلٹروں سے اٹی ہوئی مرزئی کو لپیٹ لپاٹ کر سنبھال کے آنگن کے ایک گوشے میں ٹوٹے ہوئے گھڑے پر رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ سیدھا میرے پاس آیا۔ اور غیر متوقع جرأت سے اس نے سوال کیا۔
’’کتنا مشارا دو گے؟‘‘
میں نے کہا۔۔۔ ’’ٹھکانے سے کام کر۔ کھانا، کپڑا، مشاہرہ سب ملیں گے۔‘‘
کہنے لگا، نہیں بول دو کتنا ملے گا؟‘‘
میں نے ہنس کر کہا، ’’ابے تو مشاہرہ لے کے کیا کرے گا؟ خوب بھر پیٹ کھایا کر اور پیسے لے لیا کر دو ایک۔‘‘
’’اونہہ! تب ہم نہیں رہیں گے۔‘‘
’’مشاہرہ بھی ملے گا تو گھبراتا کیوں ہے؟ تیرا گھر کہاں ہے؟‘‘ میں نے اسے تسلی دی۔
مجپھڑ پور جلع۔‘‘
میں نے دریافت کیا، ’’ماں باپ ہیں؟‘‘
اس نے کہا، ’’نہیں! کوئی نہیں!‘‘ اور نفی میں زور سے سر ہلاتا رہا۔
’’بھائی بہن؟‘‘
’’کہہ تو دیا کوئی نہیں۔‘‘ وہ بگڑ سا گیا۔
’’اچھا تجھے مشاہرہ دوں گا۔ میرے پاس جمع کرانا، اس سے بہت سے کپڑے بنا لینا اور مٹھائیاں کھانا۔‘‘
’’نہیں مشاہرہ ہاتھ میں لیں گے۔‘‘
’’ہاتھ میں لے کر کیا کرے گا؟ پھینک دے گا اور کیا! یا گر جائیں گے روپے کہیں۔‘‘
’’نہیں! ہم کو مکان بنانا ہے۔‘‘ اس نے شان و وقار کے ساتھ کہا۔ میں بھی چونک گیا اور سب لوگ ہنسنے لگے۔ اسے چوٹ سی لگی کہنے لگا۔
’’میرے بھی مکان ہے جی! جلجلہ میں گر گیا ہے تھوڑا۔ دو کوٹھڑی ہے! اس کے سیاہ چہرے پر خون نے دھپے ہوئے توے کا رنگ پیدا کر دیا۔
میں نے کہا، ’’اچھا بنانا مکان۔ تیرے ہاتھ میں روپے دوں گا۔‘‘ وہ خوش ہو گیا اور ہنسنے لگا۔ اس نے یہ بھی نہ پوچھا پھر کتنا مشاہرہ ہوگا۔ اس کے دل میں بھی حسرت تعمیر اور تمنائے ملکیت تھی۔ اسی حسرت، اسی تمنا کے پورا ہونے کا تصور ہی اتنا خوش آئند تھا کہ وہ سرمست ہو گیا۔
وہ مکان کے بیرونی احاطے میں جا کر بیٹھ رہا۔ جب اسے کسی کام کے لیے بلایا جاتا تو وہ چلا آتا اور کام کو ادھورا ہی چھوڑ کر پھر باہر احاطے میں جا بیٹھتا۔ اسے ایک دو بار سمجھانے کی کوشش کی گئی مگر وہ اپنی جگہ پر اٹل تھا۔ ہم لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ ابھی زور دینا ٹھیک نہیں چپ ہو رہے کہ کہیں وہ بھاگ نہ جائے۔ اب رات ہو چلی اور وہ مزے میں صحن میں بیٹھا رہا۔ کھانا کھانے کے لیے اندر آیا اور پھر باہر چل دیا۔ بڑی دقتوں سے اسے سلانے کے لیے اندر لایا گیا۔ اب وہ کوٹھری کے اندر سونے پر رضامند نہیں۔ رات بھر وہ سائبان ہی میں سوتا رہا۔ غضب کی سردی تھی مگر وہ تو کھلی فضا کا پنچھی تھا۔ اسے اوڑھنے کے لیے ایک کمبل دے دیا گیا جسے اس نے نہایت استغنا کے ساتھ سرسری طور پر لے لیا۔
صبح ہوتے ہی وہ احاطے میں جا پہنچا۔ صرف قمیص اور ہاف پینٹ پہنے ہوئے، اسے بلا کر چولھے کے پاس باورچی خانے میں بٹھایا گیا۔ وہاں وہ چپکا بیٹھا رہا۔ جب ہم لوگوں کے ناشتے کے بعد اسے روٹی کھانے کو مل چکی تو میرے پاس آیا اور کہنے لگا۔
’’ہم جا کے چادر لی آویں؟‘‘
میں نے پوچھا، ’’کہاں ہے تیری چادر؟‘‘
اس نے نہایت صفائی سے جواب دیا، ’’فٹ پاتھ پر۔‘‘
’’ارے فٹ پاتھ پرکہاں؟‘‘
’’جہاں ہم روج سوتے تھے۔ آحاطہ کے ٹٹی میں لٹکا کے رکھ دیا ہے۔‘‘ اب وہ جانے کے لیے بے چین تھا۔
میں نے کہا۔۔۔ ’’تجھے دوسری چادر مل جائے گی مت جا!‘‘
مگر اس نے ایک نہ سنی اور جانے پر مصر ہوا۔ ملازموں نے اسے زبردستی روکنا چاہا تو وہ زورزور سے رونے لگا۔
میں نے آخرش اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ چھلانگ لگا کر احاطے کے اندر چلا گیا اور وہاں سے یک بیک لوٹ کر اندر آیا۔ اس نے صحن کے گوشے میں جا کر قمیص اتار دی۔ اپنا میلا سا ربود کرتہ اور مرزئی پہنی اور ہاتھ میں لنگوٹی کا چیتھڑا لے کر باہر جانے لگا۔
میں نے اسے کہا، ’’ارے یہ کیا! اپنی چادر لے کر تو واپس نہیں آئے گا کیا؟‘‘ وہ بلا جواب دیے پھرتی سے احاطے سے باہر نکل گیا اور پھاٹک سے باہر ہوکر دوڑتا ہوا بھاگا۔ یہ جا وہ جا۔
فٹ پاتھ اسے آواز دے رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں کی آواز سن لی۔ کل کا بھولا بچہ اپنے گھر لوٹ چکا تھا۔