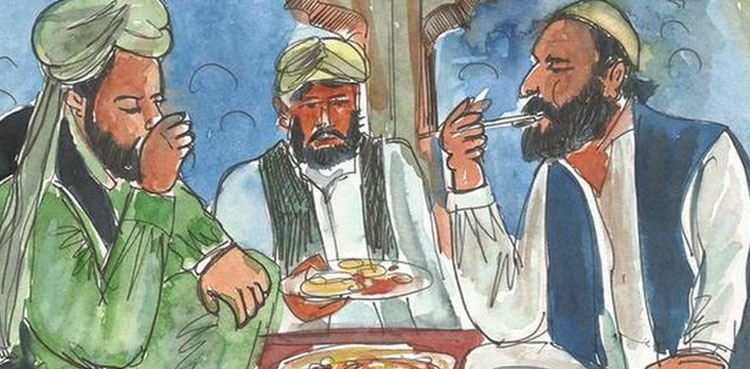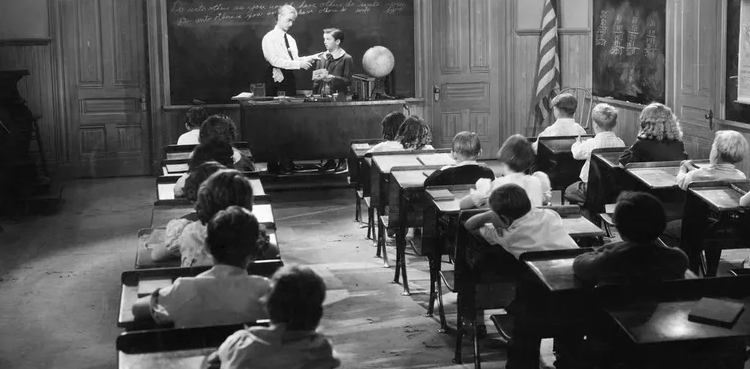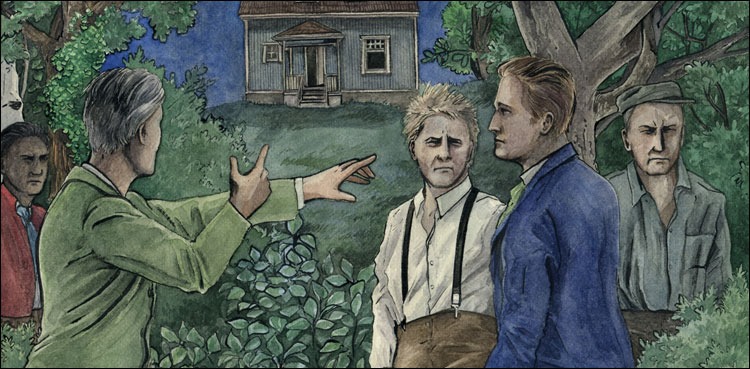نانی پیار سے اسے سِلیا ہی کہتی تھی۔ بڑے بھیّا نے اپنی تعلیم یافتہ سوجھ بوجھ کے ساتھ اس کا نام شیلجا رکھا تھا۔ وہ ماں باپ کی سلّی رانی تھی۔ سِلیا گیارھویں کلاس میں پڑھ رہی تھی۔ سانولی سلونی معصوم، بھولی، سیدھی اور سنجیدہ مزاج سِلیا اپنی اچھی صحّت کی وجہ سے اپنی عمر سے کچھ زیادہ ہی لگتی تھی۔ اسی سال 1960 کا سب سے زیادہ عجیب واقعہ ہوا۔
ہندی اخبار ’نئی دنیا‘ میں اشتہار چھپا، ’’اچھوت خاندان کی بہو چاہیے۔‘‘ مدھیہ پردیش کی راجدھانی بھوپال کے جانے مانے نوجوان نتیا سیٹھ جی، اچھوت لڑکی کے ساتھ بیاہ کر کے سماج کے سامنے ایک مثال رکھنا چاہتے تھے۔ ان کی صرف ایک شرط تھی کہ لڑکی کم سے کم میٹرک ہو۔
مدھیہ پردیش کے ہوشنگ آباد ضلع کے اس چھوٹے گاؤں میں بھی اشتہار کو پڑھ کر ہلچل مچی ہوئی تھی۔ گاؤں کے پڑھے لکھے لوگوں نے، برہمن بنیوں نے سِلیا کی ماں کو صلاح دی، تمھاری بیٹی تو میٹرک پڑھ رہی ہے، بہت ہوشیار اور سمجھ دار بھی ہے، تم اس کا فوٹو، نام پتہ اور تعارف لکھ کر بھیج دو۔ تمھاری بیٹی کے تو نصیب کھل جائیں گے، راج کرے گی۔ سیٹھ جی بہت بڑے آدمی ہیں۔
سِلیا کی ماں زیادہ جرح میں نہ پڑ کر صرف اتنا ہی کہتی ہے۔‘‘ ہاں بھیّا جی، ہاں دادا جی….! ہاں بائی جی، سوچ سمجھ لیں۔‘‘
سِلیا کے ساتھ پڑھنے والی سہیلیاں اسے چھیڑتیں، ہنسی مذاق کرتیں مگر سِلیا اس بات کا کوئی سَر پیر نہیں سمجھ پاتی۔ اسے بڑا عجیب لگتا۔ ’’کیا کبھی ایسا بھی ہوسکتا ہے؟‘‘
اس بارے میں گھر میں بھی ذکر ہوتا رہتا۔ پڑوسی اور رشتے دار کہتے۔’’فوٹو اور نام پتہ بھیج دو۔‘‘
تب سِلیا کی ماں اپنے گھر والوں کو اچھی طرح سمجھا کر کہتی۔ ’’نہیں بھیّا یہ سب بڑے لوگوں کے چونچلے ہیں، آج سب کو دکھانے کے لیے میری بیٹی کے ساتھ شادی کریں گے اور کل چھوڑ دیا تو ہم غریب لوگ ان کا کیا کر لیں گے؟ اپنی عزت اپنے سماج میں رہ کر ہی ہوسکتی ہے۔ دکھاوے کی چار دن کی عزت ہمیں نہیں چاہیے۔ ہماری بیٹی ان کے خاندان اور سماج میں ویسی عزت اور قدر نہیں پاسکے گی۔ ہم سے بھی دور کر دی جائے گی، ہم تو نہیں دیویں اپنی بیٹی کو۔ ہم اس کو خوب پڑھائیں گے، لکھائیں گے، اس کی قسمت میں ہو گا تو اس سے زیادہ عزت وہ خود پا لے گی۔‘‘
بارہ سال کی سِلیا ڈری سہمی ایک کونے میں کھڑی تھی اور مامی اپنی بیٹی مالتی کو بال پکڑ کر مار رہی تھی۔ ساتھ ہی زور زور سے چِلّا کر کہتی جا رہی تھی ’’کیوں ری تجھے نہیں معلوم، اپنے وا کنویں سے پانی نہیں بھر سکے ہیں؟ کیوں چڑھی تو وہاں کنویں پر، کیوں رسّی بالٹی کو ہاتھ لگایا؟‘‘ اور جملہ پورا ہونے کے ساتھ ہی دو چار تھپڑّ، گھونسے اور برس پڑے مالتی پر۔ بے چاری مالتی دونوں ہاتھوں میں اپنا منہ چھپائے چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ ساتھ ہی کہتی جا رہی تھی۔ ’’او بائی معاف کر دے اب ایسا کبھی نہیں کروں گی۔‘‘
مامی کا غصہ اور مالتی کا رونا دیکھ کر سِلیا اپنے آپ کو مجرم محسوس کر رہی تھی۔ اپنی صفائی میں بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس مار پیٹ کے سلسلے میں اس کی آواز دھیمی پڑ جاتی۔ مامی کا تھوڑا غصہ کم ہوتا دیکھ سِلیا نے ہمّت بٹوری۔ ’’مامی میں نے تو مالتی کو منع کیا تھا مگر وہ مانی نہیں۔ کہنے لگی جیجی پیاس لگی ہے، پانی پئیں گے۔‘‘
مامی بپھر کر بولیں۔ ’’گھر کتنا دور تھا، مَر تو نہیں جاتی، مَر ہی جاتی تو اچھا تھا۔ اس کی وجہ سے اسے کتنی باتیں سننی پڑیں۔‘‘ مامی نے دُکھ اور افسوس کے ساتھ اپنا ماتھا ٹھونکتے ہوئے کہا تھا۔’’ہے بھگوان تو نے ہماری کیسی جات بنائی۔‘‘
سِلیا نیچے دیکھنے لگی، سچ بات تھی۔ گاڈری محلے کے جس کنویں سے مالتی نے پانی نکال کر پیا تھا۔ وہاں سے بیس پچیس قدم پر ہی ماما مامی کا گھر تھا جس کی رسی، بالٹی اور کنویں کو چُھو کر مالتی نے ناپاک کر دیا تھا۔
وہ عورت بکریوں کے ریوڑ پالتی تھی۔ گاڈری محلے کے زیادہ تر گھروں میں بھیڑ بکریوں کو پالنے کا اور انھیں بیچنے خریدنے کا کاروبار کیا جاتا تھا۔ گاڈری محلّے سے لگ کر ہی آٹھ دس گھر بھنگی سماج کے تھے۔
سِلیا کے مامی ماما یہیں رہتے تھے۔ مالتی سِلیا کی ہی ہم عمر تھی۔ بس سال چھے مہینے چھوٹی ہو گی، مگر حوصلہ اس میں بہت زیادہ تھا۔ جس کام کو نہ کرنے کی نصیحت اسے کی جائے اسی کام کو کر کے وہ خطرے کا سامان کرنا چاہتی تھی۔ سلیا سنجیدہ اور سادہ مزاج کی کہنا ماننے والی فرماں بردار لڑکی تھی۔
مالتی کو روتا دیکھ کر اسے خراب ضرور لگا، مگر وہ اس بات کو سمجھ رہی تھی کہ اس میں مالتی کی ہی غلطی ہے۔ جب ہمیں پتہ ہے ہم اچھوت دوسروں کے کنویں سے پانی نہیں لے سکتے تو پھر وہاں جانا ہی کیوں؟‘‘ وہ بکری والی کیسے چِلّا رہی تھی۔ ’’دیکھو تو منع کرنے کے بعد بھی کنویں سے پانی بھر رہی ہے۔ ہماری رسی بالٹی خراب کر دی….‘‘ اور مامی کو اس نے کتنی باتیں سنائی تھیں: تہارے نزدیک رہتے ہیں تو کا ہمارا کوئی دھرم کرم نہیں ہے؟ کا مرضی ہے تمھاری۔ صاف صاف کہہ دو؟‘‘
مامی گڑ گڑا رہی تھی۔’’بائی جی، معاف کر دو۔ اتنی بڑی ہو گئی مگر عقل نہیں آئی اس کو۔ کتنا تو مارو ہوں۔‘‘ مامی وہیں سے مالتی کو مارتی ہوئی گھر لائی تھیں۔ ’’بیچاری مالتی!‘‘ سِلیا سوچ رہی تھی بھگوان اسے جلدی سے عقل دے۔ تب وہ ایسے کام نہیں کیا کرے گی۔
ایک سال پہلے کی بات ہے۔ پانچویں کلاس کے ٹورنامنٹ ہو رہے تھے۔ کھیل کود، کے مقابلوں میں اس نے بھی حصہ لیا تھا۔ اپنے کلاس ٹیچر اور کلاس کی لڑکیوں کے ساتھ وہ تحصیل کے اسکول میں گئی تھی۔ اس کے مقابلہ کی دوڑ شروع میں ہونے سے جلدی پوری ہو گئیں۔ وہ لمبی دوڑ اور کرسی دوڑ کی ریسوں میں اوّل آئی تھی۔ وہ اپنی کھو۔ کھو ٹیم کی کٹنچ تھی اور کھو کھو کے کھیل میں اس کی وجہ سے جیت ملی تھی۔
اس کے ٹیچر گوکل پرساد ٹھاکر جی نے سب کے سامنے اس کی بہت تعریف کی تھی۔ ساتھ ہی پوچھا تھا، ’’ شیلجا‘‘ یہاں تحصیل میں تمھارے رشتے دار رہتے ہوں گے۔ تم وہاں جانا چاہتی ہو تو بتاؤ ہم پہنچا دیں گے۔‘‘ سِلیا ماما، مامی کے گھر کا پتہ جانتی تھی مگر ٹیچروں کے سامنے شرم کے مارے وہ نہیں بتا پائی۔ اس نے کہا، ’’مجھے تو یہاں کسی کا بھی پتہ نہیں معلوم۔‘‘ تب سر نے اس کی سہیلی ہیم لتا سے کہا تھا ’’اسے اپنی بہن کے گھر لے جاؤ، شام کو سبھی ایک ساتھ گاؤں لوٹیں گے، تب تک یہ وہاں آرام کر لے گی۔‘‘ ہیم لتا ٹھاکر سِلیا کے ساتھ ہی پانچویں کلاس میں پڑھتی تھی۔ اس کی بڑی بہن کا سسرال تحصیل میں تھا۔ ان کا گھر تحصیل کے اسکول کے پاس ہی تھا۔
وہ سِلیا کو لے کر بہن کے گھر آئی۔ بہن کی ساس نے ہنس کر ان کا استقبال کیا۔ ہیم لتا کو پانی کا گلاس دیا۔ دوسرا گلاس ہاتھ میں لے کر سِلیا سے پوچھنے لگی، ’’کون ہے، کس کی بیٹی ہے؟ کون ٹھاکر ہے؟ سِلیا کچھ کہہ نہ سکی۔ ہیم لتا نے کہا ’موسی جی، میری سہیلی ہے، ساتھ میں آئی ہے۔ اس کے ماما مامی یہاں رہتے ہیں مگر اسے ان کا پتہ معلوم نہیں ہے۔‘‘ بہن کی ساس اسے دھیان سے دیکھتے ہوئے سوچتی ہے۔ پھر ہیم لتا سے اس کی ذات کے بارے میں پوچھتی ہے۔ ہیم لتا نے دھیرے سے بتا دیا۔ اسے لگا ذات کے بارے میں سن کر موسی جی ایک منٹ کے لیے چونکی۔ پھر انھوں نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے سلیا سے پوچھا۔ ’’گاڈری محلہ کے پاس رہتے ہیں۔‘‘
سِلیا نے ہاں کہہ کر سَر جھکا لیا۔ تب موسی جی نے بہت پیار جتاتے ہوئے کہا ’’کوئی بات نہیں بیٹی، ہمارا بھیا تمھیں سائیکل پر بٹھا کر چھوڑ آئے گا، ایسا کہتے ہوئے موسی جی پانی کا گلاس لے کر واپس اندر چلی گئیں۔ سلیا کو پیاس لگی تھی۔ مگر وہ موسی جی سے پانی مانگنے کی ہمّت نہیں کرسکی۔ موسی جی کے بیٹے نے اسے گاڈری محلے کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ سِلیا راستے بھر کڑھتی آ رہی تھی۔ آخر اسے پیاس لگی تو اس نے موسی جی سے پانی کیوں نہیں مانگ کر پیا۔ تب موسی کے چہرے پر ایک پل کے لیے آیا۔ رنگ اُس کی نظروں میں تیر گیا۔ کتنا مکھوٹا چڑھائے رکھتے ہیں یہ لوگ۔ موسی جی جانتی تھیں کہ اسے پیاس لگی ہے۔ پر ذات کا نام سن کر پانی کا گلاس لوٹا لے گئی۔ ’’کیا وہ پانی مانگنے پر انکار کر دیتی؟‘‘ سِلیا کو یہ سوال کچوک رہا تھا۔
سلیا کو دیکھ کر ماما، مامی اور مالتی بہت خوش تھے۔ بڑے جوش و خروش سے ملے تھے۔ مگر سِلیا، ہیم لتا کی بہن کی سسرال سے ملی گھٹن کو بھول نہیں پا رہی تھی۔ شام کے وقت ماما نے اسے اسکول پہنچا دیا تھا۔ سلیا کا مزاج پریشان کن بنتا جا رہا تھا۔ ریت رواج سے الگ نئے نئے خیال اس کے من میں آئے۔ وہ سوچتی ’’آخر مالتی نے کون سا جرم کیا تھا۔ پیاس لگی، پانی نکال کر پی لیا۔‘‘ پھر وہ سوچتی، ’’ہیم لتا کی موسی جی سے وہ پانی کیوں نہیں لے سکی تھی؟ اور اب یہ اشتہار اونچے گھرانے کا نوجوان، سماجی کارندہ، ذات پات کے بھید بھاؤ مٹانے کے لیے نیچ ذات کی اچھوت لڑکی سے شادی کرے گا…. یہ سیٹھ جی مہاشے کا ڈھونگ ہے۔ دکھاوا ہے یا وہ سچ مچ کے سماج کے ریت رواج بدلنے والے سماجی انقلاب لانے والے مہان آدمی ہیں؟ اس کے دل میں یہ خیال بھی آتا کہ اگر اسے اپنی زندگی میں ایسے کسی مہان آدمی کا ساتھ ملا تو وہ اپنے سماج کے لیے بہت کچھ کر سکے گی۔ لیکن کیا کبھی ایسا ہوسکتا ہے؟
یہ سوال اس کے من سے ہٹتا نہیں تھا۔ ماں کے سچ کی بنیاد پر کیے گئے تجربات پر اس کا اٹوٹ یقین تھا۔ مدھیہ پردیش کی زمین میں 60ء تک ایسی فصل نہیں اُگی تھی جو ایک چھوٹے گاؤں کی اچھوت جانی جانے والی بھولی بھالی لڑکی کے من میں اپنا اعتبار قائم کرسکتی۔ اور پھر دوسروں کے رحم و کرم پر عزت؟ اپنی خود داری کو کھو کر دوسروں کی شطرنج کا مہرہ بن کر رہ جانا، بیساکھیوں پر چلتے ہوئے جینا، نہیں کبھی نہیں۔
سِلیا سوچتی۔’’ہم کیا اتنے لاچار ہیں، بے بس ہیں، ہماری اپنی بھی تو کچھ آن عزت ہے۔ انھیں ہماری ضرورت ہے۔ ہم کو ان کی ضرورت نہیں۔ ہم ان کے بھروسے کیوں رہیں۔ پڑھائی کروں گی، پڑھتی رہوں گی، تعلیم کے ساتھ اپنی شخصیت کو بھی بڑا بناؤں گی۔ ان سبھی رسم و رواج کی وجوہات کا پتہ لگاؤں گی جنھوں نے انھیں اچھوت بنا دیا ہے۔
علم، عقل اور تمیز سے اپنے آپ کو اونچا ثابت کر کے رہوں گی۔ کسی کے سامنے جھکوں گی نہیں۔ نہ یہ بے عزتی سہوں گی۔‘‘ ان باتوں کو دل ہی دل میں سوچتی اور دہراتی سلیا ایک دن اپنی ماں اور نانی کے سامنے کہنے لگی۔ ’’میں شادی کبھی نہیں کروں گی۔‘‘
ماں اور نانی اپنی بھولی بھالی بیٹی کو دھیان سے دیکھتی رہ گئیں۔ نانی خوش ہو کر بولی،’’شادی تو ایک نہ ایک دن کرنی ہی ہے بیٹی۔ مگر اس کے پہلے تو خوب پڑھائی کر لے۔ اتنی بڑی بن جا کہ بڑی ذات کے کہلانے والے کو اپنے گھر نوکر رکھ لینا۔‘‘
ماں دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی۔ سوچ رہی تھی۔ ’’میری سلو رانی کو میں خوب پڑھاؤں گی۔ اسے عزت کے لائق بناؤں گی۔‘‘
(سشیلا ناک بھورے کی ہندی کہانی کے مترجم ف س اعجاز ہیں)